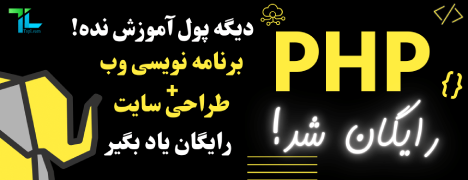داستان گوئی ایک فن ہے جس میں داستان کو لوگوں کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ اس فن کا تعلق 13ویں صدی سے ہے۔ داستان نثری افسانوی ادب ہے۔ اس میں کہانی کو ممکن حد تک طول دیا جاتا ہے۔ قصے در قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان قصوں کی بنیاد خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ داستان درحقیقت مافوق الفطرت کہانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فارسی طرز کی داستان گوئی کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی لیکن دھیرے دھیرے یہ فن ختم ہوتا گیا۔ تاہم سنہ 2005ء میں اس فن کا دوبارہ احیا کیا گیا اور ہندوستان اور بیرون ہند میں داستان گوئی کے سینکڑوں جلسے منعقد کیے گئے۔ مطبوعہ داستان کے اولین نمونوں میں داستان امیر حمزہ ہے جو 46 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔
برصغیر ہند میں یہ فن 19ویں صدی میں اپنے عروج پر پہونچا اور میر باقر علی داستان گو کی موت کے ساتھ یہ بھی مرگیا۔ ہندوستانی شاعر اور نقاد شمس الرحمان فاروقی اور ان کے بھتیجے، کاتب اور ڈائرکٹر محمود فاروقی نے 21ویں صدی میں اس کے احیا کے لیے کا رہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔
داستان گوئی کا سب سے مرکزی کردار داستان گو ہے۔ جس کی آواز ہی ایک آرٹ ہے۔ وہ کہانی میں اپنی آواز کا جادو شامل کرکے داستان کی اثر انگیزی کو بام عروج تک پہونچا دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے ممتاز داستان گو میں امبا پرساد رسا، میر احمد علی رامپوری، محمد عامر خان، سید حسین جاہ اور غلام رضا ہیں۔
داستان گوئی ایک فارسی لفظ ہے۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو اور گو کا مطلب ہے کہنے والا یا سنانے والا چنانچہ داستان گو کے معنی ایسا شخص جو داستان سنائے۔
ہندوستانی داستان گوئی کو درباری داستان گوئی یا ہندوی داستان گوئی بھی کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کے ادیب اور شاعر امیر خسرو کے شیخ مشہور صوفی نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ بیمار پڑے تو امیر خسرو نے انکی طبیعت بہلانے کے لیے قصہ چہار درویش/ باغ و بہار اور الف لیلہ و لیلہ کی کہانیوں کے مجموعے انکو سنائے۔ جب تینوں کہانیاں ختم ہوگئیں تو نظام الدین اولیا بالکل ٹھیک ہو گئے اور فرمایا کہ جو بیمار ان تین کہانیوں کو سن لے تو شفایاب ہوگا۔
داستان گوئی کی تاریخ
ماہر بشریات غوث انصاری کے مطابق داستان گوئی کی جڑیں قبل از اسلام عرب سے ملتی ہیں۔ پھر اسلام کی اشاعت نے اس فن کو ایران تک تک پہونچایا اور ایران والے ہندوستان دہلی لیکر آئے۔ 1857ء کی بغاوت کے بعد جب لوگ دہلی سے لکھنؤ پہونچے تو دوسری اصناف ادب کے ساتھ ساتھ داستان گوئی بھی لکھنؤ گئی۔
داستان گوئی لکھنؤ کیا گئی مانو اپنے پیا کے گھر پہونچ گئی۔ وہاں اس کو خوب سراہا گیا۔ داستان گوئی کے جلسے چوراہوں، گلی محلوں، گھروں اور افیم خانوں میں ہونے لگے۔ غوث انصاری لکھتے ہیں: “نشئیوں کے درمیان میں داستان گوئی اتنی مشہور ہوئی کی ان کے اجتماع کا اہم حصہ سمجھی جانے لگی۔” ان کے دماغ پر افیم کے نشے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا نشہ بھی چڑھنے لگا اور دونوں نشے عموماً ایک ساتھ افیم خانوں میں کیے جاتے تھے۔ ہر افیم خانہ کا ایک داستان گو ہوتا تھا جو سامعین کو محظوظ کرتا تھا۔ ہر امیر گھرانے کے عملے میں ایک داستان گو ضرور ہوتا تھا۔ لکھنؤ کے 19ویں صدی کے تاریخ داں اور مصنف عبد الحلیم شرر لکھتے ہیں کہ داستان گوئی کا فن جنگ، خوشی، خوبصورتی، محبت اور دھوکا جیسی سرخیوں میں منقسم تھا۔
پرانے داستان گو جادو، جنگ اور مہم جوئی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور عربی کہانی جیسے الف لیلہ، کہانی نگار جیسے رومی اور کہانی و داستان کے مراجع جیسے پنچ تنتر سے کہانیاں مستعار لیا کرتے تھے۔ 14 ویں صدی سے فارسی داستان گوئی کا موضوع پیغمبر محمد کے چچا امیر حمزہ کی زندگی اور ان کے حیرت انگیز کارنامے ہونے لگے۔ ہندوستانی داستان گوئی میں عیاری دھوکا بھی شامل ہونے لگی۔
داستان گوئی کی روایت کو مختف زبانوں میں رواج دینے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ 2017ء کے کولکاتا عالمی کتاب میلہ میں ابھیشیک سرکار کی ایک ناول “داستان گوئی” کو ایک بنگالی ناشر ترتیو پریسر نے شائع کیا۔ یہ ناول ایک داستان گو کی 1990ء کی سیاسی گہماگہمی کے بعد آنے والے دنوں کی منظر کشی کرتا ہے۔ تین شہروں کولکاتا، علی گڑھ اور دہلی کے ادبی ماحول میں شاہ نامہ، حمزہ نامہ اور سکندر نامہ کی کہانیوں کی دنیا سجی رہتی ہے۔
16ویں صدی میں پنپنے والی داستان گوئی کی صنف کا سلسلہ ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کا انتقال 1928ء میں ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داستان گوئی کے قواعد کے بارے میں زیادہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔[1]
محمود فاروقی نے اپنے چچا شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ مل کر داستان گوئی کے قدیم فن کو دوبارہ زندہ کیا ہے[2]
[3][4][5][6]
داستان گوئی ایک فن ہے جس میں داستان کو لوگوں کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ اس فن کا تعلق 13ویں صدی سے ہے۔ داستان نثری افسانوی ادب ہے۔ اس میں کہانی کو ممکن حد تک طول دیا جاتا ہے۔ قصے در قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان قصوں کی بنیاد خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ داستان درحقیقت مافوق الفطرت کہانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فارسی طرز کی داستان گوئی کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی لیکن دھیرے دھیرے یہ فن ختم ہوتا گیا۔ تاہم سنہ 2005ء میں اس فن کا دوبارہ احیا کیا گیا اور ہندوستان اور بیرون ہند میں داستان گوئی کے سینکڑوں جلسے منعقد کیے گئے۔ مطبوعہ داستان کے اولین نمونوں میں داستان امیر حمزہ ہے جو 46 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔
برصغیر ہند میں یہ فن 19ویں صدی میں اپنے عروج پر پہونچا اور میر باقر علی داستان گو کی موت کے ساتھ یہ بھی مرگیا۔ ہندوستانی شاعر اور نقاد شمس الرحمان فاروقی اور ان کے بھتیجے، کاتب اور ڈائرکٹر محمود فاروقی نے 21ویں صدی میں اس کے احیا کے لیے کا رہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔
داستان گوئی کا سب سے مرکزی کردار داستان گو ہے۔ جس کی آواز ہی ایک آرٹ ہے۔ وہ کہانی میں اپنی آواز کا جادو شامل کرکے داستان کی اثر انگیزی کو بام عروج تک پہونچا دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے ممتاز داستان گو میں امبا پرساد رسا، میر احمد علی رامپوری، محمد عامر خان، سید حسین جاہ اور غلام رضا ہیں۔
داستان گوئی ایک فارسی لفظ ہے۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو اور گو کا مطلب ہے کہنے والا یا سنانے والا چنانچہ داستان گو کے معنی ایسا شخص جو داستان سنائے۔
ہندوستانی داستان گوئی کو درباری داستان گوئی یا ہندوی داستان گوئی بھی کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کے ادیب اور شاعر امیر خسرو کے شیخ مشہور صوفی نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ بیمار پڑے تو امیر خسرو نے انکی طبیعت بہلانے کے لیے قصہ چہار درویش/ باغ و بہار اور الف لیلہ و لیلہ کی کہانیوں کے مجموعے انکو سنائے۔ جب تینوں کہانیاں ختم ہوگئیں تو نظام الدین اولیا بالکل ٹھیک ہو گئے اور فرمایا کہ جو بیمار ان تین کہانیوں کو سن لے تو شفایاب ہوگا۔
داستان گوئی کی تاریخ
ماہر بشریات غوث انصاری کے مطابق داستان گوئی کی جڑیں قبل از اسلام عرب سے ملتی ہیں۔ پھر اسلام کی اشاعت نے اس فن کو ایران تک تک پہونچایا اور ایران والے ہندوستان دہلی لیکر آئے۔ 1857ء کی بغاوت کے بعد جب لوگ دہلی سے لکھنؤ پہونچے تو دوسری اصناف ادب کے ساتھ ساتھ داستان گوئی بھی لکھنؤ گئی۔
داستان گوئی لکھنؤ کیا گئی مانو اپنے پیا کے گھر پہونچ گئی۔ وہاں اس کو خوب سراہا گیا۔ داستان گوئی کے جلسے چوراہوں، گلی محلوں، گھروں اور افیم خانوں میں ہونے لگے۔ غوث انصاری لکھتے ہیں: “نشئیوں کے درمیان میں داستان گوئی اتنی مشہور ہوئی کی ان کے اجتماع کا اہم حصہ سمجھی جانے لگی۔” ان کے دماغ پر افیم کے نشے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا نشہ بھی چڑھنے لگا اور دونوں نشے عموماً ایک ساتھ افیم خانوں میں کیے جاتے تھے۔ ہر افیم خانہ کا ایک داستان گو ہوتا تھا جو سامعین کو محظوظ کرتا تھا۔ ہر امیر گھرانے کے عملے میں ایک داستان گو ضرور ہوتا تھا۔ لکھنؤ کے 19ویں صدی کے تاریخ داں اور مصنف عبد الحلیم شرر لکھتے ہیں کہ داستان گوئی کا فن جنگ، خوشی، خوبصورتی، محبت اور دھوکا جیسی سرخیوں میں منقسم تھا۔
پرانے داستان گو جادو، جنگ اور مہم جوئی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور عربی کہانی جیسے الف لیلہ، کہانی نگار جیسے رومی اور کہانی و داستان کے مراجع جیسے پنچ تنتر سے کہانیاں مستعار لیا کرتے تھے۔ 14 ویں صدی سے فارسی داستان گوئی کا موضوع پیغمبر محمد کے چچا امیر حمزہ کی زندگی اور ان کے حیرت انگیز کارنامے ہونے لگے۔ ہندوستانی داستان گوئی میں عیاری دھوکا بھی شامل ہونے لگی۔
داستان گوئی کی روایت کو مختف زبانوں میں رواج دینے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ 2017ء کے کولکاتا عالمی کتاب میلہ میں ابھیشیک سرکار کی ایک ناول “داستان گوئی” کو ایک بنگالی ناشر ترتیو پریسر نے شائع کیا۔ یہ ناول ایک داستان گو کی 1990ء کی سیاسی گہماگہمی کے بعد آنے والے دنوں کی منظر کشی کرتا ہے۔ تین شہروں کولکاتا، علی گڑھ اور دہلی کے ادبی ماحول میں شاہ نامہ، حمزہ نامہ اور سکندر نامہ کی کہانیوں کی دنیا سجی رہتی ہے۔
16ویں صدی میں پنپنے والی داستان گوئی کی صنف کا سلسلہ ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کا انتقال 1928ء میں ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داستان گوئی کے قواعد کے بارے میں زیادہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔[1]
محمود فاروقی نے اپنے چچا شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ مل کر داستان گوئی کے قدیم فن کو دوبارہ زندہ کیا ہے[2]
[3][4][5][6]
داستان گوئی ایک فن ہے جس میں داستان کو لوگوں کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ اس فن کا تعلق 13ویں صدی سے ہے۔ داستان نثری افسانوی ادب ہے۔ اس میں کہانی کو ممکن حد تک طول دیا جاتا ہے۔ قصے در قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان قصوں کی بنیاد خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ داستان درحقیقت مافوق الفطرت کہانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فارسی طرز کی داستان گوئی کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی لیکن دھیرے دھیرے یہ فن ختم ہوتا گیا۔ تاہم سنہ 2005ء میں اس فن کا دوبارہ احیا کیا گیا اور ہندوستان اور بیرون ہند میں داستان گوئی کے سینکڑوں جلسے منعقد کیے گئے۔ مطبوعہ داستان کے اولین نمونوں میں داستان امیر حمزہ ہے جو 46 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔
برصغیر ہند میں یہ فن 19ویں صدی میں اپنے عروج پر پہونچا اور میر باقر علی داستان گو کی موت کے ساتھ یہ بھی مرگیا۔ ہندوستانی شاعر اور نقاد شمس الرحمان فاروقی اور ان کے بھتیجے، کاتب اور ڈائرکٹر محمود فاروقی نے 21ویں صدی میں اس کے احیا کے لیے کا رہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔
داستان گوئی کا سب سے مرکزی کردار داستان گو ہے۔ جس کی آواز ہی ایک آرٹ ہے۔ وہ کہانی میں اپنی آواز کا جادو شامل کرکے داستان کی اثر انگیزی کو بام عروج تک پہونچا دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے ممتاز داستان گو میں امبا پرساد رسا، میر احمد علی رامپوری، محمد عامر خان، سید حسین جاہ اور غلام رضا ہیں۔
داستان گوئی ایک فارسی لفظ ہے۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو اور گو کا مطلب ہے کہنے والا یا سنانے والا چنانچہ داستان گو کے معنی ایسا شخص جو داستان سنائے۔
ہندوستانی داستان گوئی کو درباری داستان گوئی یا ہندوی داستان گوئی بھی کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کے ادیب اور شاعر امیر خسرو کے شیخ مشہور صوفی نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ بیمار پڑے تو امیر خسرو نے انکی طبیعت بہلانے کے لیے قصہ چہار درویش/ باغ و بہار اور الف لیلہ و لیلہ کی کہانیوں کے مجموعے انکو سنائے۔ جب تینوں کہانیاں ختم ہوگئیں تو نظام الدین اولیا بالکل ٹھیک ہو گئے اور فرمایا کہ جو بیمار ان تین کہانیوں کو سن لے تو شفایاب ہوگا۔
داستان گوئی کی تاریخ
ماہر بشریات غوث انصاری کے مطابق داستان گوئی کی جڑیں قبل از اسلام عرب سے ملتی ہیں۔ پھر اسلام کی اشاعت نے اس فن کو ایران تک تک پہونچایا اور ایران والے ہندوستان دہلی لیکر آئے۔ 1857ء کی بغاوت کے بعد جب لوگ دہلی سے لکھنؤ پہونچے تو دوسری اصناف ادب کے ساتھ ساتھ داستان گوئی بھی لکھنؤ گئی۔
داستان گوئی لکھنؤ کیا گئی مانو اپنے پیا کے گھر پہونچ گئی۔ وہاں اس کو خوب سراہا گیا۔ داستان گوئی کے جلسے چوراہوں، گلی محلوں، گھروں اور افیم خانوں میں ہونے لگے۔ غوث انصاری لکھتے ہیں: “نشئیوں کے درمیان میں داستان گوئی اتنی مشہور ہوئی کی ان کے اجتماع کا اہم حصہ سمجھی جانے لگی۔” ان کے دماغ پر افیم کے نشے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا نشہ بھی چڑھنے لگا اور دونوں نشے عموماً ایک ساتھ افیم خانوں میں کیے جاتے تھے۔ ہر افیم خانہ کا ایک داستان گو ہوتا تھا جو سامعین کو محظوظ کرتا تھا۔ ہر امیر گھرانے کے عملے میں ایک داستان گو ضرور ہوتا تھا۔ لکھنؤ کے 19ویں صدی کے تاریخ داں اور مصنف عبد الحلیم شرر لکھتے ہیں کہ داستان گوئی کا فن جنگ، خوشی، خوبصورتی، محبت اور دھوکا جیسی سرخیوں میں منقسم تھا۔
پرانے داستان گو جادو، جنگ اور مہم جوئی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور عربی کہانی جیسے الف لیلہ، کہانی نگار جیسے رومی اور کہانی و داستان کے مراجع جیسے پنچ تنتر سے کہانیاں مستعار لیا کرتے تھے۔ 14 ویں صدی سے فارسی داستان گوئی کا موضوع پیغمبر محمد کے چچا امیر حمزہ کی زندگی اور ان کے حیرت انگیز کارنامے ہونے لگے۔ ہندوستانی داستان گوئی میں عیاری دھوکا بھی شامل ہونے لگی۔
داستان گوئی کی روایت کو مختف زبانوں میں رواج دینے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ 2017ء کے کولکاتا عالمی کتاب میلہ میں ابھیشیک سرکار کی ایک ناول “داستان گوئی” کو ایک بنگالی ناشر ترتیو پریسر نے شائع کیا۔ یہ ناول ایک داستان گو کی 1990ء کی سیاسی گہماگہمی کے بعد آنے والے دنوں کی منظر کشی کرتا ہے۔ تین شہروں کولکاتا، علی گڑھ اور دہلی کے ادبی ماحول میں شاہ نامہ، حمزہ نامہ اور سکندر نامہ کی کہانیوں کی دنیا سجی رہتی ہے۔
16ویں صدی میں پنپنے والی داستان گوئی کی صنف کا سلسلہ ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کا انتقال 1928ء میں ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داستان گوئی کے قواعد کے بارے میں زیادہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔[1]
محمود فاروقی نے اپنے چچا شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ مل کر داستان گوئی کے قدیم فن کو دوبارہ زندہ کیا ہے[2]
[3][4][5][6]
داستان گوئی ایک فن ہے جس میں داستان کو لوگوں کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ اس فن کا تعلق 13ویں صدی سے ہے۔ داستان نثری افسانوی ادب ہے۔ اس میں کہانی کو ممکن حد تک طول دیا جاتا ہے۔ قصے در قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان قصوں کی بنیاد خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ داستان درحقیقت مافوق الفطرت کہانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فارسی طرز کی داستان گوئی کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی لیکن دھیرے دھیرے یہ فن ختم ہوتا گیا۔ تاہم سنہ 2005ء میں اس فن کا دوبارہ احیا کیا گیا اور ہندوستان اور بیرون ہند میں داستان گوئی کے سینکڑوں جلسے منعقد کیے گئے۔ مطبوعہ داستان کے اولین نمونوں میں داستان امیر حمزہ ہے جو 46 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔
برصغیر ہند میں یہ فن 19ویں صدی میں اپنے عروج پر پہونچا اور میر باقر علی داستان گو کی موت کے ساتھ یہ بھی مرگیا۔ ہندوستانی شاعر اور نقاد شمس الرحمان فاروقی اور ان کے بھتیجے، کاتب اور ڈائرکٹر محمود فاروقی نے 21ویں صدی میں اس کے احیا کے لیے کا رہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔
داستان گوئی کا سب سے مرکزی کردار داستان گو ہے۔ جس کی آواز ہی ایک آرٹ ہے۔ وہ کہانی میں اپنی آواز کا جادو شامل کرکے داستان کی اثر انگیزی کو بام عروج تک پہونچا دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے ممتاز داستان گو میں امبا پرساد رسا، میر احمد علی رامپوری، محمد عامر خان، سید حسین جاہ اور غلام رضا ہیں۔
داستان گوئی ایک فارسی لفظ ہے۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو اور گو کا مطلب ہے کہنے والا یا سنانے والا چنانچہ داستان گو کے معنی ایسا شخص جو داستان سنائے۔
ہندوستانی داستان گوئی کو درباری داستان گوئی یا ہندوی داستان گوئی بھی کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کے ادیب اور شاعر امیر خسرو کے شیخ مشہور صوفی نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ بیمار پڑے تو امیر خسرو نے انکی طبیعت بہلانے کے لیے قصہ چہار درویش/ باغ و بہار اور الف لیلہ و لیلہ کی کہانیوں کے مجموعے انکو سنائے۔ جب تینوں کہانیاں ختم ہوگئیں تو نظام الدین اولیا بالکل ٹھیک ہو گئے اور فرمایا کہ جو بیمار ان تین کہانیوں کو سن لے تو شفایاب ہوگا۔
داستان گوئی کی تاریخ
ماہر بشریات غوث انصاری کے مطابق داستان گوئی کی جڑیں قبل از اسلام عرب سے ملتی ہیں۔ پھر اسلام کی اشاعت نے اس فن کو ایران تک تک پہونچایا اور ایران والے ہندوستان دہلی لیکر آئے۔ 1857ء کی بغاوت کے بعد جب لوگ دہلی سے لکھنؤ پہونچے تو دوسری اصناف ادب کے ساتھ ساتھ داستان گوئی بھی لکھنؤ گئی۔
داستان گوئی لکھنؤ کیا گئی مانو اپنے پیا کے گھر پہونچ گئی۔ وہاں اس کو خوب سراہا گیا۔ داستان گوئی کے جلسے چوراہوں، گلی محلوں، گھروں اور افیم خانوں میں ہونے لگے۔ غوث انصاری لکھتے ہیں: “نشئیوں کے درمیان میں داستان گوئی اتنی مشہور ہوئی کی ان کے اجتماع کا اہم حصہ سمجھی جانے لگی۔” ان کے دماغ پر افیم کے نشے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا نشہ بھی چڑھنے لگا اور دونوں نشے عموماً ایک ساتھ افیم خانوں میں کیے جاتے تھے۔ ہر افیم خانہ کا ایک داستان گو ہوتا تھا جو سامعین کو محظوظ کرتا تھا۔ ہر امیر گھرانے کے عملے میں ایک داستان گو ضرور ہوتا تھا۔ لکھنؤ کے 19ویں صدی کے تاریخ داں اور مصنف عبد الحلیم شرر لکھتے ہیں کہ داستان گوئی کا فن جنگ، خوشی، خوبصورتی، محبت اور دھوکا جیسی سرخیوں میں منقسم تھا۔
پرانے داستان گو جادو، جنگ اور مہم جوئی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور عربی کہانی جیسے الف لیلہ، کہانی نگار جیسے رومی اور کہانی و داستان کے مراجع جیسے پنچ تنتر سے کہانیاں مستعار لیا کرتے تھے۔ 14 ویں صدی سے فارسی داستان گوئی کا موضوع پیغمبر محمد کے چچا امیر حمزہ کی زندگی اور ان کے حیرت انگیز کارنامے ہونے لگے۔ ہندوستانی داستان گوئی میں عیاری دھوکا بھی شامل ہونے لگی۔
داستان گوئی کی روایت کو مختف زبانوں میں رواج دینے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ 2017ء کے کولکاتا عالمی کتاب میلہ میں ابھیشیک سرکار کی ایک ناول “داستان گوئی” کو ایک بنگالی ناشر ترتیو پریسر نے شائع کیا۔ یہ ناول ایک داستان گو کی 1990ء کی سیاسی گہماگہمی کے بعد آنے والے دنوں کی منظر کشی کرتا ہے۔ تین شہروں کولکاتا، علی گڑھ اور دہلی کے ادبی ماحول میں شاہ نامہ، حمزہ نامہ اور سکندر نامہ کی کہانیوں کی دنیا سجی رہتی ہے۔
16ویں صدی میں پنپنے والی داستان گوئی کی صنف کا سلسلہ ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کا انتقال 1928ء میں ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داستان گوئی کے قواعد کے بارے میں زیادہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔[1]
محمود فاروقی نے اپنے چچا شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ مل کر داستان گوئی کے قدیم فن کو دوبارہ زندہ کیا ہے[2]
[3][4][5][6]
ہم سب مل کر چلیں گے
کچھ سال قبل ایک گھریلو محفل میں ہم ایک جدید داستان گو دانش حسین کے اطراف دلچسپی اور استعجاب کے عالم میں غرق ’’داستانِ امیر حمزہ‘‘ کا ایک حصہ سن رہے تھے۔ جملوں کا بہاؤ، زبان کی سلاست، اندازِ بیاں، آواز کا زیرو بم اور داستان طلسم ہوشربا کا سحر، غرض سارے کمالات کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ویسے بھی داستانوں کے سحر میں گرفتار ہونا تو انسان کے جبلی خواص میں شامل ہے۔ کچھ لمحوں کیلئے ایسا لگا کہ جیسے ہم ایک صدی قبل جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے شائقین ہیں کہ جہاں داستان گو اپنے فن کا جادو جگاتے تھے یا پھر اور پیچھے چلے جائیں کہ جب قرونِ وسطیٰ کے ایران میں سردیوں میں جلتے الاؤ سے جسم سینکتے ہوئے سڑکوں یا قہوہ خانوں میں داستانیں سننے کی روایت اپنے کمال پر تھی۔
اگلے وقتوں میں جب فلم، تھیٹر، ٹی وی جیسی تفریحات ناپید تھیں، داستان گوئی کا فن تفریح کا اہم ذریعہ تصور کیا جاتا تھا اور عوام و خواص میں یکساں مقبول تھا۔ اگر محض ایک صدی قبل کے ہندوستان میں جھانکیں تو عوام الناس اگر چوک اور نکڑوں پر تصوراتی دنیاؤں کی سیر کو نکلتے تو خواص اپنے ایوانوں اور محلوں میں طلسماتی دنیاؤں کے مزے لوٹتے۔ اس فن کے زوال تک بھی جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر داستان گو اپنی زبانی داستان سے شائقین کے ہوش و حواس کو تسخیر کر لیتے تھے۔
داستان گوئی کی تاریخ
داستان گوئی کی ابتدائی تاریخ کا حتمی طور پر کوئی پتہ نہیں ملتا تاہم اُردو میں اس فن کی منتقلی ابتدا میں عربی سے فارسی زبان (ایران) کے ذریعہ ہندوستان تک پہنچی۔ ان داستانوں میں سے سب سے مشہور ’’داستانِ امیر حمزہ‘‘ ہے۔ ہم میں سے اکثر اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ ان کی بنیاد دراصل حضرت محمد مصطفیؐ کے چچا حضرت امیر حمزہؓ اور ان کے ساتھیوں کی جنگی شجاعت کے کارناموں پر رکھی گئی ہے اور اس کا مقصد ان کے جذبہ ایمانی، برائیوں کے خلاف صف آرائی اور جرأت مندی کا عَلم بلند کرنے کو بیان کرنا تھا۔ ان میں سے ایک اہم کردار عمروعیار کا تھا جو بحیثیت امیر حمزہ کے معاون ساتھی کے اپنی جادوئی عیاری کی مدد سے دشمن کو زیر کرنے میں ان کی مدد کرتا۔ امیر حمزہ اور عمروعیار کا مجموعہ پہلی بار 1100 عیسوی میں داستان کی صورت میں شائع ہوا۔
گو ان داستانوں کا ایک بڑا مقصد شہنشاہوں کو تفریح مہیا کرنا تھا، تاہم ان کو فنی کمال پر پہنچانے کا اصل فریضہ اور داد تو ان داستان گو افراد کو جاتی ہے کہ جو سادہ رقم کی ہوئی داستان کو بہت سارے لوازمات سے آراستہ کرتے جس میں زبان کی چاشنی، لہجہ کی بناوٹ، مکالموں کی ادائیگی وغیرہ شامل ہے۔ بیٹھے بیٹھے یا ایک جگہ کھڑے ہوئے محض جسمانی اعضاء کی حرکات و سکنات، آواز کا اتار چڑھاؤ، مرصع شاعری کے ملاپ سے جادو، عیاری، خیر و شر، حسن و طرب کی بزموں کا سماں گویا آج کے جدید تھیٹر کا سماں پیدا کرنا کہ سننے والے داستان گو کے اعجازِ بیاں سے کسی اور جہاں کے مزے لوٹنے لگتے۔ بیان کی ادائیگی میں خاص خیال رکھا جاتا کہ لہجہ اور زبان کو مقامی علاقہ کے انداز میں ڈھالا جائے تاکہ داستان سے اپنائیت کا احساس ہو۔
یہ داستانیں نویں صدی سے بیسویں صدی تک تفریح کا مقبول ذریعہ رہیں۔ ہندوستان میں حمزہ نامہ یا داستانِ امیر حمزہ کو مغلیہ شہنشاہ اکبر اعظم کے عہد میں عروج حاصل ہوا۔ اکبر کے دربار کے نو رتن میں فیضی اور ابوالفضل نے ان داستانوں کو جمع کیا۔ اس طرح حقیقت تو یہ ہے کہ ان داستانوں کو تصویری پیرہن سے آراستگی کا فریضہ اکبر کے دور کا اہم کارنامہ ٹھہرا کہ جب انکی تصویری عکاسی کپڑے پر مبنی 1400 تصاویر سے کی گئی۔ اسکا بنیادی کام ایرانی فنکار سید علی اور خواجہ عبدالصمد کی نگرانی میں ہوا۔
کئی جلدوں پر مبنی ان تصویری فولیو کی تکمیل 15 سال (1562-1577) میں انجام پائی۔ تصویر کا سائز 74x58CM تھا۔ تصاویر کی پشت پر عربی نستعلیق رسم الخط میں داستان کا متن ہوتا اور دوسری جانب منظر کی تصویر کشی۔ دو افراد اس کو پکڑتے اور داستان گو بیان دیتا۔ اس طرح گویا یہ اس زمانے کا کوئی ٹی وی ڈرامہ ہوتا۔ ان تصاویر کو البرٹ اور وکٹوریہ میوزیم میں محفوظ کرنے کا سہرا ڈون کلارک کے سر ہے۔ افسوس کہ نہ صرف ہم نے اس فن کو کھویا بلکہ اس کے بچے کھچے آثار کو بھی اپنا ثقافتی ورثا بناکر محفوظ نہ رکھ سکے۔
اٹھارہویں اور 19 ویں صدی میں فارسی زبان سے اُردو میں منتقلی کے بعد داستان گوئی کے اس فن کو مزید وسعت ملی اور اس کا اثر ادب کی دوسری اصناف پر بھی مرتب ہوا۔ 1880ء کے بعد تقریباً دو دہائیوں تک داستانِ امیر حمزہ لکھنؤ کے گلی کوچوں اور نکڑوں میں چھائی رہی اور یہی حال دہلی میں بھی اسکی مقبولیت کا تھا تاہم اس پرانے فن میں سماجی ڈھانچہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ زوال پیدا ہونے لگا۔ اس کی ایک وجہ غالباً داستانوں میں بزمِ حسن و طرب کا ذکر جو اسلامی ثقافت میں معیوب سمجھا جاتا تھا، تو دوسری جانب ریفارمسٹ تحریک تھی جو 1857ء کے بعد کے دور میں پیدا ہوئی۔ اس کے تحت ان داستانوں کو بوسیدہ فن کی شکل قرار دیا گیا۔
صدی کے آخری داستان گو میر باقر علی کو بیسویں صدی کے اواخر میں دہلی کے بازار میں پان، چھالیہ بیچتے دیکھا گیا۔ یہ وہ فنکار تھا جو امراء کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی فنکاروں کی دنیا سے رخصتی کے بعد اپنے گھر میں داستان گوئی کی محفل منعقد کرتا۔ میر باقر کی آواز میں بیان کی ہوئی تین منٹ کی داستان آج بھی تبرکاً لندن کی لائبریری کے خزینہ میں قیمتی اور نایاب اثاثے کی صورت میں محفوظ ہے۔ بعد کے سالوں میں داستان گوئی کی جگہ بائی سکوپ اور تھیٹر نے لے لی اور یوں مشینی دوڑ میں یہ فن کہیں کچل کر وقت کی دھول میں دب گیا اور بالآخر بیسویں صدی میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ تقسیم ہند کے بعد بہت سے سنجیدہ ادیبوں مثلاً محمد حسن عسکری، پروفیسر سہیل احمد خان اور گیان چند جین نے ان داستانوں کی تہوں میں چھپی ہوئی معنویت اور حقیقت پسندی کے گوہر تلاش کئے اور اپنے تحقیقی مضامین میں اس کا ذکر کیا۔ آج کے عہد کے ادیب شمس الرحمن فاروقی کہ جن کا شمار جدید ادب کے حامیوں میں ہوتا ہے، 46 ضخیم جلدوں پر مشتمل ’’داستانِ امیر حمزہ‘‘ کو یکجا کیا۔ اسکی ہر جلد تقریباً 900 صفحات پر مشتمل ہے۔
دور جدید کے داستان گو اس قدیم فن کو دوبارہ جلا بخش رہے ہیں اور دنیا میں ہر اس جگہ اپنی داستان گوئی کا فن پیش کر رہے ہیں کہ جہاں اُردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ چند اہم نام دہلی کے دانش حسین (جو فلموں کے بھی فنکار ہیں)، محمود فاروقی جو شمس الرحمن فاروقی کے بھانجے ہیں اور فلم کے علاوہ مختلف تھیٹر گروپس سے بھی وابستہ ہیں۔ فواد خان اور کینیڈا کے جاوید دانش بھی داستان گوئی کی ترویج میں اہم کردار ادا کررہے ہیں۔ ان فنکاروں نے ماضی کے داستان گو فنکاروں کا مخصوص لباس انکرکھا پاجامہ اور ٹوپیاں پہن کر ماضی کی داستانوں کو ایک بار پھر خواص و عوام کی محافل بنا دیا ہے تاکہ فن کے دفن خزینہ کو ایک بار پھر جلا ملے۔ یہ تمام فنکار یقیناً قابل تحسین ہیں خصوصاً اس عہد میں کہ جب اُردو کے ساتھ اس کے سگے بھی سوتیلوں جیسا سلوک روا رکھ رہے ہیں۔
ایک نمونہ دیکھیئے:
admin
12 اکتوبر, 2018
مضامین
تبصرہ کریں
1,223 بار پڑھا گیا
اردو میں تاریخ گوئی اور داستان گوئی کی روایت اور فن
احمد مد سہیل
داستان گوئی کی تاریخ
تاریخ گوئی اور داستان گوئی ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہوئے انھیں ایک دوسرے سے ممیز بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور دونوں کا خمیر یکسان طور پر گندھا ہوا ہے۔ اس کا اثر ہندوستانی اور پاکستاںی ڈرامہ اور تھیڑیکل میدان پر گہرا نظر آتا ہے۔ داستان گوئی اور تاریخ گوئی کی نظری مبادیات کو تین نکات میں منقسم کیا جاسکتا ہے:
۱۔ راوی،۔۔۔۔۔ قصہ گو کی صورت میں ایک کہانی یا داستان میں موجود ہوتا ہے۔
۲۔ زبانی داستان گوئی، تاریخ گوئی ، رویت، اساطیر تاریخ اور ثقافت کے روایتی سلسلے ہوتے ہیں
۳۔ داستان گوئی، الفاظ، تصاویر اور آواز کے زیر وبم کے زریعے سے واقعات کو برجستگی سے ابلاغ کرتے ہیں۔
فنِ تاریخ گوئی سے مراد کسی شعر، مصرع یا نثر کے حروف کے ابجد سے کسی واقعہ کی تاریخ کا برآمد کرنا ہے۔ یہ روایت اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ہے۔ جو شعر برآمد ہو اسے ‘مادہ’ یا مادۂ تاریخ’ کہا جاتا ہے۔ فارسی و اردو میں یہ ‘تاریخ’ اور عربی میں قطعہ تاریخ اور ترکی میں یہ ‘رمز’ بھی کہلاتا ہے۔ اردو میں یہ روایت کئی صدیوں سے جاری ہے مگر اب اس کا رواج اردو سے عدم واقفیت کی بناء پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ تاریخ گوئی بامعنی الفاظ کے زریعے کسی واقعے کی تاریخ، بحساب ابجد نکلالنا ہے۔ اور تاریخ کو حتمی طور پر متعین کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ دن مہینہ سال ایک جملے یا مصرعے سے اخذ کی جاسکتی ہے۔۔ اسے ” مادہ تاریخ ” کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ پچیچدگی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور ” تاریخ گوئی” کی ہیت کا مخاطبہ تشکیک اور ابہام کا شکار ہوکر ” معمہ گوئی” کی شکل بھی اختیار کرکے چیستانی سوال کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ داستان گوئی کا دہلی میں سب سے زیادہ چرچا رہا اور یہاں داستان گوئی کے فن کے کو ایک پرفارمنس آرٹ کے طور پر رواج دیتے ہوئے، داستان کے بیانیہ اظہار کو خلقی اور نیا رنگ عطا کیا۔ اور یہ فن ارتقا کی منازل طے کرتا رہا۔ روایت ہے کہ ایک نشست میں میر تقی میر نے بھی داستاں گوئی کے جوہر دکھائے تھے۔ داستان سے اپنی گہری دلچسپی کا اظہار اپنے خطوط میں ملتا ہے۔ مگر غدر کے ہنگامے کے بعد داستان گوئی کا فن اٹھ کر لکھنّو چلا گیا۔ اور بھر یہ فن اودہ اور رام پور کے دربار میں ” داستان گویاں” کے نام سے معروف ہوا۔ اس کے علاوہ مرثیہ گوئی کے زیر اثر داستان سرائی میں حرکات اور سکنات، لب ولہجہ اور اعضئا اشارے اور جنبش سے داستان گوئی میں تنوع پیدا ہوا۔ سہیل بخاری کے بقول
دراصل پورے ایشیائی ادب کا مزاج عاشقانہ ہے اس لیے داستان بھی محبت کے جذبے سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتی تھی۔ داستان کے ہیرو کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی ایسی ہستی کا انتخاب کیا جائے جو مافوق الفطرت عناصر اور کم سے کم عمال، وزراء اور امراء کی شکل میں پیش کیے جائیں کیوں کہ ہیرو کو عوام سے بالاتر اور محکم تر پیش کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ہیرو میں چند انتہائی صفات ہوتی ہیں۔ وہ بے پناہ حسن کے ساتھ ساتھ وفا کا پتلا بھی ہوتا ہے ۔ ہیروئن عاشق کے لیے یہاں تک ایثار کرتی ہے کہ والدین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے ۔ داستان ”بیثرن و منیثرہ“ میں منیثرہ کی جرأت مندانہ صلاحیتوں کی بنا پر روایتی اقدار کے باوجود اپنے عاشق کے لیے ہمت و جرأت کا اظہار ملتا ہے ۔ دیو، دیونی اور بھوت پریت کا ذکر تقریباً کسی نہ کسی صورت میں کم و بیش ہر داستان میں ہوتا ہے ۔ یہ ایک ایسی آتشی خلقت ہے جو عموماً مشاہدے میں نہیں آتی مگر ان کا وجود تحریر و تقریر میں موجودہوتا ہے ۔ گویا آنکھوں سے نہیں دیکھا کانوں سے سنا ہے ، ذہنوں میں ان کا وجود جاگزیں ہے اور انھیں غیر معمولی قوتوں کا حامل سمجھا جاتا ہے ۔”۔
داستانوں کے پلاٹ میں زیادہ تنوع نہیں ہوتا۔ تمام قصے کچھ ان خطوط پر چلتے ہیں کہ ہیرو کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ اسے راہ میں بہت سے حوادث، دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ تمام مصائب کا وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے اور فتح یاب ہوتا ہے ۔ جہاں تک داستان کی اصل غایت کا تعلق ہے وہ کہانی کی غایت سے مختلف نہیں۔ زیادہ تر داستانوں کے موضوعات ہلکے پھلکے عشقیہ و تفریحی ہوتے ہیں۔ کچھ داستانیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں اخلاق آموزی، تہذیب نفس، عالمانہ دقیقہ سنجی، مذہب اور تخلیق پر زور دیا جاتا ہے ۔ لیکن یہ تمام باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور داستان کی اصل غایت میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ داستانی تکنیک کو کلچرل، اخلاقی اور دیگر مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے تاکہ سننے والے یا پڑھنے والے ان داستانوں کو درس آموز کلیات کے طور پر شعوری یا لاشعوری طور پر ذہن نشیں کر سکیں۔ داستانوں میں اخلاقی تعلیم یا مذہبی عناصر بھی موجود ہوتے ہیں یعنی معلمین اخلاق اور علمبرداران مذہب نے بھی داستان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے ۔ ان کے ایسا کرنے کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اخلاق و مذہب کے مبادیات تفریحی مطالعہ کے طور پر آسانی سے سمجھائے جا سکتے ہیں۔ تفریح اور عشق کا التزام کسی نہ کسی داستان میں ضرور ملتا ہے ۔ اس کے علاوہ عجائب نگاری کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے ۔ طلسم و سحر، نیرنگ و فسوں پر دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے جاتے ہیں۔ بقول صغیر افراہیمداستان دراصل زندگی اور اس کی حقیقتوں سے فرار کا دوسرا نام ہے ۔ خواہشات کی تکمیل جب حقیقی عنوان سے نہ ہو پاتی تو تخیل کے سہارے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی اس لیے انسان جب اپنے حالات سے فرار حاصل کرتا تو عموماً داستانوں کی دنیا میں پہنچ کر ذہنی و قلبی سکون حاصل کرتا۔ سہیل بخاری کے بقول دراصل پورے ایشیائی ادب کا مزاج عاشقانہ ہے اس لیے داستان بھی محبت کے جذبے سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتی تھی۔ داستان کے ہیرو کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی ایسی ہستی کا انتخاب کیا جائے جو مافوق الفطرت عناصر اور کم سے کم عمال، وزراء اور امراء کی شکل میں پیش کیے جائیں کیوں کہ ہیرو کو عوام سے بالاتر اور محکم تر پیش کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ہیرو میں چند انتہائی صفات ہوتی ہیں۔ وہ بے پناہ حسن کے ساتھ ساتھ وفا کا پتلا بھی ہوتا ہے ۔ ہیروئن عاشق کے لیے یہاں تک ایثار کرتی ہے کہ والدین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے ۔ داستان ”بیثرن و منیثرہ“ میں منیثرہ کی جرأت مندانہ صلاحیتوں کی بنا پر روایتی اقدار کے باوجود اپنے عاشق کے لیے ہمت و جرأت کا اظہار ملتا ہے ۔ دیو، دیونی اور بھوت پریت کا ذکر تقریباً کسی نہ کسی صورت میں کم و بیش ہر داستان میں ہوتا ہے ۔ یہ ایک ایسی آتشی خلقت ہے جو عموماً مشاہدے میں نہیں آتی مگر ان کا وجود تحریر و تقریر میں موجودہوتا ہے ۔ گویا آنکھوں سے نہیں دیکھا کانوں سے سنا ہے ، ذہنوں میں ان کا وجود جاگزیں ہے اور انھیں غیر معمولی قوتوں کا حامل سمجھا جاتا ہے ۔”۔ داستان گوئی دراصل براہ راست لوگوں کے سامنے پیش کیا جانے والا فن ہی ہے،
داستانوں کے پلاٹ میں زیادہ تنوع نہیں ہوتا۔ تمام قصے کچھ ان خطوط پر چلتے ہیں کہ ہیرو کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ اسے راہ میں بہت سے حوادث، دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ تمام مصائب کا وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے اور فتح یاب ہوتا ہے ۔ جہاں تک داستان کی اصل غایت کا تعلق ہے وہ کہانی کی غایت سے مختلف نہیں۔ زیادہ تر داستانوں کے موضوعات ہلکے پھلکے عشقیہ و تفریحی ہوتے ہیں۔ کچھ داستانیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں اخلاق آموزی، تہذیب نفس، عالمانہ دقیقہ سنجی، مذہب اور تخلیق پر زور دیا جاتا ہے ۔ لیکن یہ تمام باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور داستان کی اصل غایت میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ داستانی تکنیک کو کلچرل، اخلاقی اور دیگر مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے تاکہ سننے والے یا پڑھنے والے ان داستانوں کو درس آموز کلیات کے طور پر شعوری یا لاشعوری طور پر ذہن نشیں کر سکیں۔ داستانوں میں اخلاقی تعلیم یا مذہبی عناصر بھی موجود ہوتے ہیں یعنی معلمین اخلاق اور علمبرداران مذہب نے بھی داستان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے ۔ ان کے ایسا کرنے کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اخلاق و مذہب کے مبادیات تفریحی مطالعہ کے طور پر آسانی سے سمجھائے جا سکتے ہیں۔ تفریح اور عشق کا التزام کسی نہ کسی داستان میں ضرور ملتا ہے ۔ اس کے علاوہ عجائب نگاری کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے ۔ طلسم و سحر، نیرنگ و فسوں پر دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے جاتے ہیں۔ بقول صغیر افراہیم داستان دراصل زندگی اور اس کی حقیقتوں سے فرار کا دوسرا نام ہے ۔ خواہشات کی تکمیل جب حقیقی عنوان سے نہ ہو پاتی تو تخیل کے سہارے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی اس لیے انسان جب اپنے حالات سے فرار حاصل کرتا تو عموماً داستانوں کی دنیا میں پہنچ کر ذہنی و قلبی سکون حاصل کرتا۔صفدر امام قادری نے لکھا ہے۔”اردو میں داستانوں پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اکثر اُن کی زبانی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ داستانیں تحریرکے قالب میں آنے سے پہلے زبانی روایت کا حصّہ تھیں لیکن اِسی کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رہتی ہے کہ اِن داستانوں کو قلم بند کرنے کا سلسلہ بھی اردو کے حلقے میں بھی چار پانچ سو برس سے بھی ضرور قائم ہے۔ اس میں کچھ ترجمہ اور کچھ بادشاہوں کی فرمائش کا بھی ہاتھ رہا ورنہ ’سب رس‘ جیسی کتاب آج سے تقریباً چار سو برس پہلے کیسے سامنے آگئی ہوتی۔ سچّائی یہ ہے کہ ہماری موجودہ نسل داستانوں کو تحریری شکل میں ہی پڑھتی رہی ہے اور اُن کے الفاظ یا داستانی روایت کا مکمّل عرفان ہم نے کتابوں کے مطالعے سے کِیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھاپہ خانے اور بدلتی ہوئی دنیا میں زبانی روایت کے معاملے محدود کر دیے اور رفتہ رفتہ ہم کتابوں میں سِمٹنے کے لیے مجبور ہوئے۔” برصغیر پاک وہند میں ویسے تو بہت سی داستانیں مشہور ہوئیں لیکن سب سے مشہور داستانِ امیر حمزہ تھی۔جب اسے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا تو وہ بہت پھیلتی چلی گئی۔
19 ویں صدی کے آخیر میں جب داستانِ امیر حمزہ کو چھپوانا شروع کیا گیا تو اُس کی کوئی 46 جلدیں بنیں۔ داستانِ امیر حمزہ کا ہی ایک ٹکڑا ہے طلسمِ ہوش رُبا جو نو جلدوں پر محیط ہے۔ ان 46 جلدوں کو اکٹھا کرنے اور پڑھنے اور تنقید کرنے کا کام بھارت کے نقاد شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کیا۔ قصہ گوئی کے بارے میں اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ داستان گوئی کا کمال یہ تھا کہ بڑے بڑے مجمعوں میں داستان گو اپنی داستان اگر شروع کرتا تھا تو لوگ سحر زدہ حالت میں اسے سنتے تھے۔ وہ اپنی کہانی شروع کرتا تھا درمیان میں فرض کریں بادشاہ کا ذکر آیا تو مجمع میں سے ہی ایک شخص بادشاہ کے لباس میں ملبوس بادشاہ کی کہانی شروع کر دیتا تھا۔ پھر فرض کریں ذکر آیا ملکہ کا تو ایک اور شخص ملکہ کے لباس میں موجود ملکہ کی کہانی شروع کرتا تھا۔ گویا داستان گو حضرات نے ایسا ڈرامائی تاثر قائم کیا تھا جسے ایک زمانے تک عوام میں پذیرائی ملی”۔ میر باقر علی اردو داستان گوئی اور دلی کی تہذیب کی آخری نشانی تھے ۔ داستان گوئی کے فن میں میر باقر علی نے خصوصی شہرت حاصل کی تھی۔یہ فن انہیں اپنے ننھیال سے ملا تھا۔ان کے نانا میر امیر علی اور ماموں میر کاظم علی کا تعلق دہلی دربار سےتھا ۔ یہ دونوں مانے ہوئے داستان گو تھے ۔1890 میں دہلی میں پیدا ہوئے ۔والد کا نام میر حسن علی تھا۔کم عمری میں والد کے انتقال کے بعد ننھیال میں پرورش پائی،اور غالباًنانا اور ماموں کے ساتھ محفل داستان سرائی کی محفلوں میں شرکت سے بچپن ہی سے داستان گوئی سے رغبت پیدا ہوگئی،اور ایسی رغبت پیدا ہوئی کہ اس فن میں امام کا درجہ پایا۔ انہوں نے 18مارچ 1928 کو دہلی میں انتقال فرمایا۔شاہد احمد دہلوی نے ان کی داستان گوئی کی محفل کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ “اجلی اجلی چاندنیوں کے فرش بچھ جاتے،میر صاحب کے لئے ایک چھوٹا سا تخت لگا دیا جاتا اس پر قالین اور گاؤ تکیہ ہوتا۔سامعین گاؤ تکئے سے لگ کر بیٹھ جاتے۔پان اور حقہ کا دور چلتا ۔گرمیوں میں شربت اور جاڑوں میں چائے سے تواضع کی جاتی۔یہ صاحب تخت پر براجمان ہوتے۔کٹورے یا گلاس میں پانی منگواتے ۔جیب سے چاندی کی ڈبیا اور چاندی کی چھوٹی سی پیالی نکالتے ۔ڈبیا سے افیون کی گولی نکالتے۔اسے دوائی میں لپیٹتے ۔پیالی میں تھوڑا سا پانی نکال کر اس میں گھولتے رہتے۔اور دوستوں سے باتیں کرتے رہتے۔جب ساری افیون پانی میں آجاتی تو روئی نکال کر اگالدان میں پھینک دیتے۔اور گھوٹوے کی چسکی لگا لیتے۔اس کے بعد چائے کا ایک گھونٹ پیتے۔اور فرماتے “چائے کی خوبی یہ ہے کہ لب بند ، لب ریز اور لب سوزہو”پھر داستان شروع کر دیتے۔
16ویں صدی میں پنپنے والی داستان گوئی کی صنف کا سلسلہ ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقرعلی کا انتقال 1928 میں ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داستان گوئی کے قواعد کے بارے میں زیادہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔
داستان گوئی سے متعلق مرزا اسد اللہ خاں غالب کا خیال ہے کہ ”داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے ، سچ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے ۔“ بقول کلیم الدین احمد ”داستان کہانی کی طویل پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے ۔“ گیان چند جین کے مطابق ”داستان کے لغوی معنی قصہ۔ کہانی اور افسانہ کے ہیں۔ خواہ وہ منظوم ہو یا منثور۔ جس کا تعلق زمانہ گذشتہ سے ضرور ہو اور جس میں فطری اور حقیقی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ غیر فطری، اکتسابی اور فوق العادت شاذ و نادر فوق العجائب بھی ہو سکتے ہیں۔ افسانوں کی قسموں میں داستان ایک مخصوص صنف کا نام ہو گیا تھا۔“ یورپ میں جو عاشقانہ داستانیں تصنیف کی جاتی تھیں اور ان میں کچھ کہانیاں ہیجان انگیز اور پْرکشش ہوتی تھیں وہ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں۔ ان تخیلی عاشقانہ داستانوں کو ”رومان“ کہا جاتا تھا۔ رومان کی کئی قسمیں ہوتی تھیں۔ اردو میں تاریخ گوئی اور داستان گوئی ایک عرصے سے ہورہی ہے جس پر فارسی ادبیات کا خاصا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی۔ اس سلسلے میں تسلیم سہوانی کی ” ملخص تسلیم بہ زبان فارسی {۱۸۸۵۔} ۔۔ الم کی ” گبن تاریخ”{۱۸۹۵}، کافی مشہور ہوئی۔ اس حوالے سے حافظ فیروز الدین کی ایک عمدہ کتاب” تاریخی خزانہ ” ہے۔
حوالے جات:
ہماری داستانیں۔ سیدوقار عظیم، مکتبہ عالیہ زیارت خرمہ والی۔ راج دوارہ، رامپور، یو.پی.، طبع اول نومبر1968 اردو زبان اور فنِ داستان گوئی۔ کلیم الدین احمد، ادارہ فروغ اردو امین آباد، پارک لکھنوٴ اتر پردیش اردو اکادمی لکھنوٴ اردو کی نثری داستانیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین، اتر پردیش اردو اکادمی لکھنوٴ فارسی زبان میں داستان نویسی کا آغاز و ارتقا۔ ڈاکٹر محمد استعلامی کناڈا، ترجمہ رئیس احمد نعمانی داستانوں کی تکنیک۔ ڈاکٹر گیان چند جین، رسالہ آج کل، دہلی جولائی 1955، ص8-9 اردو داستان تنقید و تحقیق۔ سہیل بخاری، پاکستان، ص۔47-50 نثری داستانوں کا سفر۔ ڈاکٹر صغیر افراہیم، ایجوکیشنل بک ہاوٴس، علی گڑھ یو.پی. ص۔22 :
“میر باقر علی داستان گو – داستانیں اور داستان گوئی ” ازعقیل عباّس جعفری، انجمن ترقی اردو، پاکستان 2014۔
ٹیگزادب مضمون
4 دن ago
4 دن ago
17 جولائی, 2019
پبلیشرز کے جھوٹ اورکچھ سوال خرم شہزاد ’ارے بھائی صاحب اب کون کتابیں پڑھتا …
آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے
تبصرہ
ای میل *
ویب سائٹ
ادارہ اردو لکھاری ڈاٹ کام مصنفین کو اشاعت کیلئے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اور قارئین کیلئے بہترین ادب کا سامان پیدا کرتا ہے، ادارے پر موجود تمام مواد مختلف لکھاریوں کی تحریریں ان کی ذاتی رائے کی عکاسی کرتی ہیں، ادارہ کسی بھی خاص رائے یا طرز فکر کو پروان نہیں چڑھاتا ، ادارہ اردو لکھاری کسی لکھاری سے متفق ہونا ضروری نہیں۔
:::”اردو میں تاریخ گوئی اور داستان گوئی کی روایت اور فن” ::: ۔-۔-۔ احمد سہیل ۔-۔-۔ تاریخ گوئی اور داستان گوئی ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہوئے انھیں ایک دوسرے سے ممیز بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور دونوں کا خمیر یکسان طور پر گندھا ہوا ہے۔ اس کا اثر ہندوستانی اور پاکستاںی ڈرامہ اور تھیڑیکل میدان پر گہرا نظر آتا ہے۔ داستان گوئی اور تاریخ گوئی کی نظری مبادیات کو تین نکات میں منقسم کیا جاسکتا ہے: ۱۔ راوی،۔۔۔۔۔ قصہ گو کی صورت میں ایک کہانی یا داستان میں موجود ہوتا ہے۔ ۲۔ زبانی داستان گوئی، تاریخ گوئی ، رویت، اساطیر تاریخ اور ثقافت کے روایتی سلسلے ہوتے ہیں ۳۔ داستان گوئی، الفاظ، تصاویر اور آواز کے زیر وبم کے زریعے سے واقعات کو برجستگی سے ابلاغ کرتے ہیں۔ فنِ تاریخ گوئی سے مراد کسی شعر، مصرع یا نثر کے حروف کے ابجد سے کسی واقعہ کی تاریخ کا برآمد کرنا ہے۔ یہ روایت اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ہے۔ جو شعر برآمد ہو اسے ‘مادہ’ یا مادۂ تاریخ’ کہا جاتا ہے۔ فارسی و اردو میں یہ ‘تاریخ’ اور عربی میں قطعہ تاریخ اور ترکی میں یہ ‘رمز’ بھی کہلاتا ہے۔ اردو میں یہ روایت کئی صدیوں سے جاری ہے مگر اب اس کا رواج اردو سے عدم واقفیت کی بناء پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ تاریخ گوئی بامعنی الفاظ کے زریعے کسی واقعے کی تاریخ، بحساب ابجد نکلالنا ہے۔ اور تاریخ کو حتمی طور پر متعین کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ دن مہینہ سال ایک جملے یا مصرعے سے اخذ کی جاسکتی ہے۔۔ اسے ” مادہ تاریخ ” کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ پچیچدگی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور ” تاریخ گوئی” کی ہیت کا مخاطبہ تشکیک اور ابہام کا شکار ہوکر ” معمہ گوئی” کی شکل بھی اختیار کرکے چیستانی سوال کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ داستان گوئی کا دہلی میں سب سے زیادہ چرچا رہا اور یہاں داستان گوئی کے فن کے کو ایک پرفارمنس آرٹ کے طور پر رواج دیتے ہوئے، داستان کے بیانیہ اظہار کو خلقی اور نیا رنگ عطا کیا۔ اور یہ فن ارتقا کی منازل طے کرتا رہا۔ روایت ہے کہ ایک نشست میں میر تقی میر نے بھی داستاں گوئی کے جوہر دکھائے تھے۔ داستان سے اپنی گہری دلچسپی کا اظہار اپنے خطوط میں ملتا ہے۔ مگر غدر کے ہنگامے کے بعد داستان گوئی کا فن اٹھ کر لکھنّو چلا گیا۔ اور بھر یہ فن اودہ اور رام پور کے دربار میں ” داستان گویاں” کے نام سے معروف ہوا۔ اس کے علاوہ مرثیہ گوئی کے زیر اثر داستان سرائی میں حرکات اور سکنات، لب ولہجہ اور اعضئا اشارے اور جنبش سے داستان گوئی میں تنوع پیدا ہوا۔ داستان گوئی سے متعلق مرزا اسد اللہ خاں غالب کا خیال ہے کہ ”داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے ، سچ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے ۔“ بقول کلیم الدین احمد ”داستان کہانی کی طویل پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے ۔“ گیان چند جین کے مطابق ”داستان کے لغوی معنی قصہ۔ کہانی اور افسانہ کے ہیں۔ خواہ وہ منظوم ہو یا منثور۔ جس کا تعلق زمانہ گذشتہ سے ضرور ہو اور جس میں فطری اور حقیقی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ غیر فطری، اکتسابی اور فوق العادت شاذ و نادر فوق العجائب بھی ہو سکتے ہیں۔ افسانوں کی قسموں میں داستان ایک مخصوص صنف کا نام ہو گیا تھا۔“ یورپ میں جو عاشقانہ داستانیں تصنیف کی جاتی تھیں اور ان میں کچھ کہانیاں ہیجان انگیز اور پْرکشش ہوتی تھیں وہ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں۔ ان تخیلی عاشقانہ داستانوں کو ”رومان“ کہا جاتا تھا۔ رومان کی کئی قسمیں ہوتی تھیں۔ اردو میں تاریخ گوئی اور داستان گوئی ایک عرصے سے ہورہی ہے جس پر فارسی ادبیات کا خاصا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی۔ اس سلسلے میں تسلیم سہوانی کی ” ملخص تسلیم بہ زبان فارسی {۱۸۸۵۔} ۔۔ الم کی ” گبن تاریخ”{۱۸۹۵}، کافی مشہور ہوئی۔ اس حوالے سے حافظ فیروز الدین کی ایک عمدہ کتاب” تاریخی خزانہ ” ہے۔ حوالے جات: ہماری داستانیں۔ سیدوقار عظیم، مکتبہ عالیہ زیارت خرمہ والی۔ راج دوارہ، رامپور، یو.پی.، طبع اول نومبر1968 اردو زبان اور فنِ داستان گوئی۔ کلیم الدین احمد، ادارہ فروغ اردو امین آباد، پارک لکھنوٴ اتر پردیش اردو اکادمی لکھنوٴ اردو کی نثری داستانیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین، اتر پردیش اردو اکادمی لکھنوٴ فارسی زبان میں داستان نویسی کا آغاز و ارتقا۔ ڈاکٹر محمد استعلامی کناڈا، ترجمہ رئیس احمد نعمانی داستانوں کی تکنیک۔ ڈاکٹر گیان چند جین، رسالہ آج کل، دہلی جولائی 1955، ص8-9 اردو داستان تنقید و تحقیق۔ سہیل بخاری، پاکستان، ص۔47-50 نثری داستانوں کا سفر۔ ڈاکٹر صغیر افراہیم، ایجوکیشنل بک ہاوٴس، علی گڑھ یو.پی. ص۔22 : {احمد سہیل}
Graduate CoursPart I (Stream A)UrduStudy Material : 1(1-18)
Contents:Part1. GhazalPart2. NazmPart 3. ProseDepartment of Urdu
Prepared by :Dr. Raisa Parveen
SCHOOL OF OPEN LEARNINGUNIVERSITY OF DELHI5,Cavalry Lane, Delhi-110007
داستان گوئی کی تاریخ
Book administration
Print book
Print this chapter
Disclaimer|Webmail|FAQs|Feedback
Express your opinions
x
Please Ask ( कृपया पूछें )
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.
اردو میں قصہ گوئی کی روایت بہت ہی قدیم ہے۔ عہد قدیم میں قصے، حکایتوں اور داستانوں کے ذیلی و ضمنی واقعات پر مشتمل ہوتے تھے۔ بقول مصنف”اردو کی نثری داستانیں“ پروفیسر گیان چند جین پرانے قصوں کے چار اہم موضوعات تھے۔ جانوروں کی کہانیاں، سحر، جنس اور جنگ وجدال۔ لیکن مذہب و اخلاق بھی موضوعات رہے ہیں، جن کامصنف مذکور نے ذکر نہیں کیا ہے۔ ان قصے کہانیوں پر بجا طو رپر قدیم سنسکرت، یونانی و رومن قصّوں سے کسی نہ کسی طورپر استفادہ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ عرب اور ایران کی قصہ گوئی کے واضح نقوش بھی ملتے ہیں لیکن یہاں صرف اردو میں قصہ گوئی کی روایت ہمارے مطالعے کا موضوع ہے۔
دکن میں شکارنامے کو چھوڑ کر چودہویں سے لے کر اٹھارہویں صدی تک نظم و نثر پر مبنی تخلیقات کا سراغ ملتاہے۔ اس دوران جوکتب ورسائل منصہ شہود پر آئے وہ اردو کی اولین تصنیفات قرار پائے۔ ان چار سو برسوں کے درمیان جوکتابیں تصنیف ہوئیں وہ زیادہ تر مذہبی، اخلاقی اوردینی نوعیت کی تھیں۔ ان میں تصوف، اخلاقیات اور مذہبی و دینی امور پر زیادہ زور ملتا ہے۔ اس دور میں خیالی یا اختراعی قصوں کا رواج بہت کم تھا۔ صرف دو تصانیف”سب رس“ اور ”طوطی نامہ“ ایسی ملتی ہیں جن میں قصے کہانیوں کا پتہ چلتاہے۔ ان میں بھی اکثرمقامات پر مذہبی اور اخلاقی رجحان و مزاج کا عمل دخل تھا۔ اٹھارہویں صدی کے آغا زمیں شمالی ہند اردو کے اہم مرکز کے طور پرابھرا۔ لیکن یہاں بھی حسب روایت قصوں میں مقصدی اورتعمیری رجحان قائم رہا۔ اس ضمن میں یہاں جو اہم تصنیف نظر آتی ہے وہ ہے”کربل کتھا“(1733) یہ کتاب ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف’روضة الشہدا“ سے ترجمہ ہے۔ فضلی کی نثر پر گرچہ عربی اور فارسی کے اثرات زیادہ تھے اور عبارت آرائی کے دوران وہ قافیہ پیمائی اور رنگینیِ بیان پرزیادہ زور صرف کرتاتھا لیکن قصہ بیان کرنے کے دوران وہ رفتہ رفتہ صاف ستھری نثر کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کربل کتھا میں دقیق اور رنگا رنگ طرز کے ساتھ ساتھ سلاست اور سہل نگاری بھی متوازی طو رپر ایک ساتھ نظر آتی ہے۔
جیسا کہ عرض کیاگیا اردو میں قدیم قصہ گوئی کے ابتدائی اور باضابطہ نمونوں میں ”سب رس“ (1935) کو اولیت کا مقام حاصل ہے۔ فضلی کے کربل کتھا کی طرح یہ بھی طبع زاد نہیں تھا۔ ملاوجہی نے اسے فارسی قصے”حسن ودل“ سے ترجمہ کیاتھا لیکن یہ وجہی کا اختصاص تھا کہ اس نے اصل میں ادنیٰ تصرف کرکے اپنی ہنر مندی کے ساتھ قصے کو اس اندا زمیں بیان کیا کہ یہ اصل کتاب پر سبقت لے گئی۔اور اس پر طبع زاد ہونے کاگمان ہونے لگا۔ فرضی قصے کی صورت میں عشق وعقل اور حسن و دل کے معرکے بیان کرنے کے دوارن اس نے مختلف تمثیلی کرداروں اور ان کے جذبات و احساسات کو اس طرح پیش کیا کہ یہ متاثر کئے بغیرنہیں رہتے۔ اس قصے سے ملاحظہ کریں چند سطور:
”ایک شہر تھا اس شہر کاناﺅں سیتاں، اس ستیاں کے بادشاہ کے ناﺅں عقل، دین ودنیا کاتمام اس تے چلتا۔ اس کے حکم باج ذرا کیں نہیں ہلتا۔ اس کے فرمائے پر جنو چلے۔ ہر دو جہاں میں ہوئے بھلے۔ دنیا میں کہوائے۔ چار لوگوں میں عزت پائے…. الحمد اللہ دونوں کوں ہوا وصال، اپنا دل خوش تو سب عالم خوش حال دل کوں ملیا جیو کاجانی، یو وصال مبارک یو خوشی ارزانی….“
ا س دور کے دوسرے نثری قصوں میں ملا سید محمد قادری کا ”طوطی نامہ“ خاصامعروف ہے۔ یہ الف لیلیٰ اور کلیلہ و دمنہ کی طرح مشہو رہوا۔ ابتدائی صورت میں اس کے 53 قصوں کو مولانا ضیاءالدین بخشی بدایونی نے مرتب کیا لیکن زبان مشکل اور ادق تھی اس لئے سید محمد قادری نے اسے سہل اور بامحاورہ زبان میں لکھا۔ مئو لف”داستانِ تاریخ اردو“ سید حامد حسن قادری کے مطابق اس قصے کو قبل میں غواصی اور ابن نشاطی بھی لکھ چکے تھے۔ بعد میں”طوطی نامہ“ کا خلاصہ ابوالفضل نے شہنشاہ اکبر کے حکم سے لکھا۔ اس طویل قصے کا ایک اقتباس دیکھیں:
داستان گوئی کی تاریخ
” بڑائی اور سنار اور درزی اور پر ہیز گار مسافری کونکلے۔ اور ایک رات بیچ جنگل دہشت بھرے ہوئے کہ پتا باگاں کاڈر سیں سے اس جنگل کا پانی ہوتاتھا۔ یکایک اپنا اس کاجاگاہ میں پڑا یعنی ہوا۔ وہ چار و یار مصلحت کرےکہ ہم ہرایک کو موافق یاری کے یک ایک پہر نگہبانی کرے۔ اول بڑائی جاگتاتھا لکڑی یک بیچ نہایت بہتری صورت کے مچھیا یعنی اچھی صورت بنایا اور پھر دوگھڑی سنار اس کے تین زیور سیں سنواریا۔ تیسری پہری میں درزی اس کے میں سات لباس کے زینت دار کہا۔ چوتھی پہری میں زاہد موں عاجزی کا طرف قبلہ کے لایا۔ دعا کیا کہ او رجان بیچ بدن اس کے پھوکے گیا ہوا۔……..“
درج بالا اقتباس کے مطالعے سے اندازہ ہوتاہے کہ چند اسماءاور ضمائر کو چھوڑ کر زبان خاصی سہل اور رواں ہے۔ ساتھ میں کہانی پن کی خصوصیت بھی موجود ہے۔ اس لےے قصے کی دلچسپی اخیر تک برقراررہتی ہے۔
سب رس ، کربل کتھا اور طوطی نامہ کی تصنیف کے عرصہ بعد فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ اس کالج کا مقصد سہل اور سلیس زبانوں میں کتابوں کا ترجمہ کراناتھا۔ تاکہ اہل ہند اور اہل برطانیہ اسے بہ آسانی سمجھ سکیں۔ اس منشا کے تحت جان گل کرائسٹ نے کالج میں کئی منشیوں کا تقرر کیا۔ اس کالج کی مساعی سے میرامن نے ”باغ وبہار“ کی تالیف کی اورشہرت کی بلندی پر پہنچے۔ باغ و بہار پہلی دفعہ 1803ءمیں طبع ہوکر منظرعام پر آئی۔ میر امن نے اس کے قصے عطا حسین تحسین کی نوطرز مرصع سے اخذ کئے تھے لیکن اپنی طرف سے یہ خوبی پید اکی کہ ادق اور بھاری بھرکم عبارتوں کی جگہ سہل اور برجستہ زبان کو ترجیح دی۔ بہتیری عبارتوں کو حذف کیا اور اپنی اختراعی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا۔ غرض کہ میرامن کی کوششوں نے اس کتاب کو اس حد تک دلچسپ اور مقبول بنادیا کہ اس کے ترجمے انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی جیسی اہم زبانون میں ہوئے۔ اس قصے کا ایک مختصر حصہ یہاں نمونتاً پیش کیاجاتاہے تاکہ اردو میں قصے کی روایت کے آغاز اور ارتقا کی بابت واقفیت ہوسکے:
”کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے جب اپنی زندگی کی امانت اجل کے فرشتے کو سونپی اور اسباب اپنی ہستی کا اس سراے فانی سے منزل باقی میں پہنچایاسو شخص نے انہیںخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا واردات گذری…. جواب دیا کہ ایک مدت تئیں عذاب عقاب کے پنجے میں سختی کے شاہین کے چنگل میں گرفتار تھا…. یک بارگی کریم کے کرم سے اس حالت سے چھٹکارا ہوا۔ سائل نے پھر سوال کیا اس کا کیا سبب ہے…. بولے کہ ایک میدان میں مسافر خانہ بنایاتھا شاید کوئی غریب راہ چلتا جیٹھ کے دنوں دوپہر کی دھوپ میں تونسا ہوا اس کے سایہ میں آنکر بیٹھا۔ …. خوش ہوکر نہایت عاجزی سے بدل دعا کی…. اس کی دعا کا تیر قبولیت کے نشانہ پر درست بیٹھا ۔ میری ا ٓمرزش ہوئی۔ اور جہنم کے گڈھے سے نکال کر بہشت کے غرفے میں رہنے کا حکم ہوا۔“
”باغ وبہار“ کی اس پرکشش اور سہل تالیف کے بعدحیدر نجش حیدری کی آرائش محفل کو بھی شہرت دوام حاصل ہوئی۔ آرائش محفل کے قصے بھی نہایت دلچسپ، سلیس اور روز مرہ کی زبان میں لکھے گئے ہیں۔نمونہ دیکھیں:
”چند روز بعدجب وہ لڑکی شعور دار ہوئی تواپنے ذہن کی رسائی اور نیک بختی کے باعث سے دائی سے کہا کہ اے مادر مہربان دنیا مانند حباب ہے۔ اس قدر دولت تنہا لےکر میں کیا کروں گی۔ مصلحت یہی ہے کہ اس کو خدا کی راہ میں لٹادوں اور آپ کو آلائشِ دنیاوی سے پاک رکھوں اور شاید نہ کروں بلکہ خدا کی یاد میں مصروف رہوں۔ اس واسطے تم سے پوچھتی ہوں کہ اس سے کس طرح چھٹکارا پاﺅں جو مناسب جانو کہو …. دائی نے کہا، اے جان پدر تو ان سات سوالوں کا اشتہار لکھ کر دروازے پر چپکادے اور یہ کہہ کر جو کوئی میرے ساتوں سوال پورے کرے گا میں اسے قبول کروںگی….“
اور جب دائی نے ان سات سوالوں کے متعلق بتایا تو حسن بانو بہت خوش ہوئی اور دل میں کہا کہ وہ کون ایسا شخص ہوگا جو ان سات سوالوں کے جواب دے گا۔ آگے کا قصہ طویل لیکن اس طرح دلچسپیوں سے بھرپور ہے کہ اس کے سحر میں آئے بغیر کوئی بھی قاری نہیں رہ سکتا۔ حیدری کی دوسری تصانیف میں”گل مغفرت“ کو نقش آخر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ بھی ”روضة الشہدا“ سے استفادہ ہے ۔ اس میں واقعات کربلا کو بہت ہی موثر اندا زمیں بیان کیاگیا ہے۔ میر امن اور حیدر بخش حیدری بلاشک وشبہ بڑے قصہ گوتھے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ میرامن چھوٹے چھوٹے جملے، ہندی الاصل الفاظ اور رو زمرہ کو برتنے میں یدطولیٰ رکھتے ہیں جبکہ حیدری عربی ، فارسی کے الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں ۔روزمرے اور محاورے کا استعمال بھی کم ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک اہم قصہ گوکی حیثیت رکھتے ہیں۔
اس سلسلے کے اہم قصہ گو شیر علی افسوس بھی تھے۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں دوران ملازمت ایک کتاب ”باغ اردو“(۳۰۸۱ئ) ترتیب دی۔ افسوس کہ یہاں گرچہ حیدری اور میرامن کے مقابلے مفرس اور معرب الفاظ ، اضافتیں اور ترکیبیں زیادہ ہیں اس کے باجوود ایک کشش ہے جو ہر جگہ اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔” گلستان سعدی“ کے ترجمے کے دوران وہ اکثر اپنی بول چال اور روز مرے سے دورجا پڑے ہیں لیکن ایک فن کاری یہ ہے کہ سعدی کے مشہور مقولے اور ضرب الامثال کو ہو بہومنتقل کردیا ہے اوراردو میں آکر یہ کافی دلچسپ اور اثرانگیز ہیں ”باغ اردو“ سے ذیل کا حصہ ملاحظہ فرمائیں:
”کہتے ہیں کہ نوشیرواں عادل کے واسطے شکار گاہ میں ایک شکا رکے کباب بھونتے تھے۔ نمک موجود نہ تھا۔ لوگوں نے زمیندار کے پاس آدمی بھیجا کہ نمک لے آﺅ۔ نوشیرواں بولا کہ نمک قیمت دے کر لیجئیو تاکہ رسم نہ بگڑ جائے۔ لوگ بولے اے بادشاہ وہ اتنی سی بات سے کیا خلل پید اہوگا۔ نوشیرواں نے کہا اولاً ظلم کی بنیاد تھوڑی ہی سی تھی جو آیا اس پر بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ اس درجہ پہنچ گئی کہ
جو کھائے شاہ رعیت کے باغ سے اےک سیب
غلام اس کے درختوں کو ڈالیں جڑ سے اکھاڑ
جو آدھے انڈے پہ سلطان ستم روا رکھے
سپاہی سیخ پہ بھونیں ہزار مرغ پچھاڑ
”باغ اردو“ کے بعد ”ہفت گلشن“ بیتال پچیسی اور شکنتلا جیسے اہم اور دلچسپ قصے ارد وکے قالب میں ڈھالے گئے۔ اس میں ہفت گلشن کو چھوڑ کر دونوں کتابیں اصلاً سنسکرت میں ہیں، لیکن اردو میں منتقل ہوکر بھی یہ اتنی ہی مقبول ہیں۔
اردو میں قصے کی ایک بہت ہی مستحکم اور مقبول روایت داستان امیر حمزہ سے قائم ہوتی ہے۔ اس کے قصے خلیل علی خاں اور عبداللہ بلگرامی نے پہلے پہل ترتیب دئے تھے۔ لیکن مطبع نول کشور کی ایما پر سید تصدق حسین نے اس کونئے سرے سے لکھا۔ وہ فسانہ عجائب کازمانہ تھا۔ فسانہ کی رنگین عبارتوں کی دھوم تھی۔ باغ و بہار کے جواب میں تخلیق کی گئی اس داستان کے سامنے داستان امیر حمزہ تھی جس کا مقابلہ ممکن نہ تھا۔ امیرحمزہ کو تصدق حسین نے شاعرانہ صنعت گری کا عجائب خانہ بنادیا۔ اس کے طول طویل قصوں میں ہندوستانی رسم و رواج اور مختلف احوال و کوائف کو شامل کرکے ہندوستانی عوام کے مذاق کے مطابق بنایا۔ بعد میں اس قصے کو مزید وسعت دے کر”طلسم ہوشربا“ کی متعدد ضخیم جلدیں تیا رکی گئیں۔ اس قصے کا آغاز یہاں ملاحظہ کریں۔ مقفیٰ و مسجع عبارتوں نے کیا حسن پیداکیا ہے:
” نخل بندان بوستان اخبار، چمن پیراہان گلستان ، تختہ کاغذ صاف میں اس طرح اشجار الفاظ موقع بموقع نصب فرماتے ہیں، صحن شفاف قرطاس کو گل دریا چین مضامین رنگا رنگ سے یوں رشک تختہ ارژنگ بناتے ہیں کہ جب باغ بیداد تیار ہوا نمونہ ہشت شداد نمودار ہوا۔ القش خوشی سے پھول گیا فکر دارین بھول گیا۔“
اردو کی بڑی اور اہم داستانوں میں ”بوستان خیال“ کا بھی شما رکیاجاتاہے۔ یہ محمد شاہ رنگیلے کے عہد کا قصہ ہے۔ اس کے مصنف میر محمد تقی ہیں۔ اردو میں اس کے پہلے مترجم خواجہ امان دہلوی ہیں لیکن ان کی وفات کے بعدان کے فرزند خواجہ قمر الدین خان نے اسے مکمل کیا۔ بوستان خیال کے ترجمے لکھنو اور دہلی دونوں دبستانوں نے اپنے اپنے طور پر کئے۔ تھوڑے سے لب ولہجے اور انداز وآہنگ کے فرق کے ساتھ پوری داستان بہر طور نہایت دلچسپ، تحیر کن اور پرکشش ہے۔ سید نادر علی نے اس داستان میں خلاف تہذیب الفاظ اور واقعات کو حذف کرکے اس طرح بنایا کہ عورتیں بچے سبھی پڑھ سکیں۔ نمونتاًا س کا ایک حصہ ملاحظہ کریں:
” اس اثنا میں شام ہوگئی۔ ناگاہ چند کنیزیں بہ لباس تکلف باغ میں آئیں اور انہوں نے بالاتفاق کہا کہ اے شہر یار آفریں ہے تم کو۔ تم کسی کنیز وخواص سے مختلط نہ ہوئے۔ ہر گاہ تمہارا استقلال مزاج ہماری ملکہ نے سنا ہے۔ دل وجان سے تم پر عاشق ہوگئی۔ اس کا کلمہ ختم کرنےکے بعد ایک نازنین…. اس شکل وصورت کی باغ میں آئی کہ اگر فرشتہ بھی ایک نظر دیکھتا، تو قوت ملکوتی سلب ہوجاتی۔ شہزادہ بے قرار ہوگیا۔ لیکن اس مکان پرسراپا فساد کے خوف سے کچھ دم نہ مارا اور جلد جلد اسم اعظم کا ورد کرنے لگا۔“
’بوستان خیال‘ اور’امیر حمزہ‘ وغیرہ کے بعد روایتی قصے کہانیوں کا ایک طویل سلسلہ دکھائی دیتاہے۔ قصہ گویوں کے یہاں ایک مشترک رواج یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی قدیم روایت اور کلچر سے قصے کشید کرتے ہیں یا کسی نہ کسی معروف فارسی ، عربی یاسنسکرت تصنیفات کااپنے انداز وآہنگ میں ترجمہ کرتے ہیں، مقصد حسن وکشش کے گل بوٹے کھلاناہوتا ہے۔ اس قبیل کے دوسرے قصوں میں قصہ گل بکاولی، چہار قصہ، افسانہ ہندی، لیلیٰ مجنوں، قصہ بندگان عالی، حکایت ہائے عجیب وغریب، قصہ بہروز سودا گر، قصہ حیرت افزا، مذہب عشق، قصہ گل وہرمز، قصہ قاضی چور، قصہ پوستی و بھنگی، قصہ چہار باغ ، قصہ رضوان شاہ ، قصہ چتر لیکھا، انوار سہیلی، شگوفہ محبت ، سہراب و رستم وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ ان قصے کہانیوں کی فی زمانہ کشش اوراہمیت رہی ہے۔
لیکن اردو میں قدیم قصے کہانیوںکی روایت اس وقت اپنا لبادہ اتار کر نئے دور میں داخل ہوجاتی ہے جب خاص اصلاحی اور تعمیری مقصد حاوی ہوتاہے۔ اس سلسلے کے مصنفین میں ڈپٹی نذیر احمد کو اولیت کا درج حاصل ہے۔ ڈپٹی نذیر کے بعدان قصوں کاایک واضح مقصد سامنے آتاہے ۔اس کے بعد عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسو ا، سرسید احمدخاں وغیرہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنی کوششوں سے کہانیوں کی سمت ورفتار کو تبدیل کرنے اور ان کے نئی راہ متعین کرنے کا اہم کارنامہ انجام دیا۔
مختصر یہ کہ اردو ادب میں قصے کہانیوں کی قدیم روایات کے غائر مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہوجاتاہے کہ اس قبیل کی تحریریں زیادہ تر دلبستگیِ خاطر اور تفریح طبع کی غرض سے خلق کی جاتی تھیں۔ معدودے چند اخلاقی اور تعمیری قصوں، جن کا ذکر اوپر ہوچکاہے ، کوچھوڑ کر کوئی واضح اور صحت مند مقصد سامنے نہیں تھا۔ بادشاہ، نوابین ، امرا اور رﺅسا وغیرہ کی مبالغہ آمیز تعریف و توصیف، ان کے جھوٹے معاشقے اور معرکے کی طول طویل داستانوں کاایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ اور اس کے پس پشت یہ نیت کارفرماتھی کہ زبان دانی کا سکہ چل جائے اور مالی اعانت بھی حاصل ہو جائے ۔گویا یہ قصے اےک طرح سے نثر میں قصیدے تھے جن کی تان حسن طلب پر ٹوٹتی تھی۔ اس لےے ان قصوں کا کوئی افادی اور دور رس نصب العین نہیں تھا۔ لیکن ادب میں اس لحاظ سے ان قصوں کی اہمیت مسلم قرار پائی کہ ان کے ابتدائی نقوش کو ہی دیکھ کر آئندہ کے قصہ گویوں اور افسانہ نگاروں نے اپنے لےے نئی راہ متعین کی اور اپنے فن پاروں کو خوب سے خوب تربنانے میں کامیاب ہوئے۔ آج اردو کے قدیم قصے ترقی کرکے اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے پوری دنیا کا سچا اور حقیقی مشاہدہ اور تجربہ کیاجاسکتاہے۔ لہٰذا آج قدیم قصے کہانیوں کی افادی اور تعمیری حیثیت جوبھی ہو لیکن ان کی تاریخی حیثیت سے انکار نہیں کیاجاسکتا۔
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.
You have remaining out of 5 free poetry pages per month. Log In or Register to become Rekhta Family member to access the full website.
You have exhausted your 5 free poetry pages per month.
Register to join Rekhta family for FREE ACCESS to full website and unique features.
Stay updated to all the latest features and event notifications on Rekhta
Rekhta Foundation
AAMOZISH
The best way to learn Urdu online
Sufinama
Online Treasure of Sufi and Sant Poetry
Qaafiya
داستان گوئی کی تاریخ
Online Urdu poetry resource for aspiring young poets
Jashn-e-Rekhta
A three-day celebration of Urdu
Rang-e-Rekhta
An Urdu karwaan tracing the roots of the Language
Shaam-e-Rekhta
A Poetic/Musical evening of Urdu saga
غزلوں 30،000+ ،شعر 20،000+ ،ای کتابوں 40،000+ میں تلاش کیجئے
آپ کی تلاش کے فوری نتائج
Rekhta Foundation
AAMOZISH
The best way to learn Urdu online
Sufinama
Online Treasure of Sufi and Sant Poetry
Qaafiya
Online Urdu poetry resource for aspiring young poets
Jashn-e-Rekhta
A three-day celebration of Urdu
Rang-e-Rekhta
An Urdu karwaan tracing the roots of the Language
Shaam-e-Rekhta
A Poetic/Musical evening of Urdu saga
Added to your favorites
Removed from your favorites
اس پوسٹ کو شیئر کریں
ای میل
فیس بک
Messenger
داستان گوئی کی تاریخ
Messenger
ٹوئٹر
وٹس ایپ
اس لنک کو کاپی کیجیے
یہ بیرونی لنک ہیں جو ایک نئی ونڈو میں کُھلیں گے
پاکستان میں تھیئٹر کی تجدید نو کے ساتھ ساتھ بعض فنکار اپنے فن کو داستان گوئی کی صنف کے ذریعے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تین سال پہلے کراچی میں تھیئٹر کے تین فنکاروں فواد خان، میسم نقوی اور نذر الحسن نے’ داستان گو’ کے نام سے ایک گروپ بنایا اور کئی صدیوں پرانی داستان گوئی کی صنف کو زندہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس تیز اور بھاگتی دوڑتی دنیا میں طویل بیانیے والی داستانیں کیسے قبول عام حاصل کر سکتی ہیں؟
فواد خان نے بتایا کہ وہ داستان گوئی میں جدت لائے ہیں۔ ‘ہم ایسے کام ڈھونڈتے ہیں جو سنانے میں مزہ آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف داستانِ امیرحمزہ سے ہی چیزیں پیش کریں۔ ہم نےجدید ادب میں موجود دیگر زبانی بیانیوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھانا شروع کیاہے۔‘
میسم نقوی نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ’جیسے ہم نےیوسفی صاحب کی آبِ گُم سے حویلی کا ایک ٹکڑا نکال کے پیش کیا، پھر عصمت چغتائی کے افسانوں کو لے کے ان کو بھی داستان کے طور پر سنانا شروع کیا اور موجودہ دور کےحساب سے اُس میں کچھ جدت کی اور کچھ انداز بھی بدلا۔ پِطرس بُخاری کی کہانیاں پیش کیں اور اسی طرح حال ہی میں ہم نے میر انیس کا مرثیہ بھی پیش کیا جو لکھا ہی سنانے کے لیے جاتا تھا۔’
داستان گو’ کے فنکاروں نے پاکستان بھر کی جامعات میں داستان گوئی کی ہے اور ہر جگہ انھیں بے حد پذیرائی ملی لیکن وہ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ زبان کی شُستگی کی وجہ سے علم و ادب سے شغف رکھنے والے بیشتر بزرگ افراد اس فن میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔
نذر الحسن نے بتایا کہ کراچی میں دا سیکنڈ فلور یا عرف عام میں مقبول ٹی ٹو ایف میں پہلی بار داستان پیش کرنے کے بعد انھیں ایک کال موصول ہوئی کہ ‘جناب میرے شوہر کی سالگرہ ہے اور انھیں داستان بہت پسند ہے تو کیا آپ پیش کرنے کے لیے آ سکیں گے؟
’ہم تقریب میں گئے اور کیک کٹنے کے بعد ہمیں تحفے کے طور پر سامنے لایا گیا۔’
داستان میں استعمال کی جانے والی زبان اب بمشکل کہیں برتی جاتی ہے اور عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ اس پرمیسم نقوی کا جواب تھا کہ ‘ داستان گو کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسے پرفارم کرے کہ سننے اور دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ ہاں وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہے اگر وہ کوئی لفظ سمجھے بھی نہیں۔’
داستان پہ ایک بڑی تنقید یہ بھی ہے کہ اس میں خواتین کو ناموس کے لفظ میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فواد خان اس بات سے سو فیصد اتفاق نہیں کرتے۔ انھوں نےمثال دیتے ہوئے کہاک ہ’طلسمِ ہوش رُبا میں خواتین جنگ بھی کر رہی ہیں، ملکہ بہار لشکروں کو لے کے چلتی ہے، ماہ رُخ لشکر کی قیادت کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ انھیں مسلمان کرنے کے بعد بولا گیا ہو کہ چلو پردو کرو اور بیٹھ جاؤ۔’
فواد خان نے مزید کہا کہ’میرا خیال ہے کہ کسی متن کو آج کے اقدار کی مطابق نہیں پرکھنا چاہیے۔ داستان کی زبان اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اسے سرے سے رد نہیں کر سکتے مثلً کیا مہا بھارت اور دیگر کلاسیکل قصے کہانیوں میں عورتوں کو صرف ایک شے کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا تو کیا آپ انھیں بھی رد کردیں گے؟’
داستان بنیادی طورپر فی البدیہہ کہی جاتی ہے لیکن اب داستان کہنےکا رواج معدوم ہو چکا ہے۔ نذر الحسن نے اسی بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ’ داستان قصے کہانیوں کی طرح لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ جو داستان اُس دور میں پروان چڑھی جب زبان اپنے عروج پر تھی۔ لوگ زندگی کی باریکیوں کو دیکھتے تھےاور انھیں داستان کی شکل میں فی البدیہہ کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حالیہ دور میں ہم ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم جو داستانیں پیش کرتے ہیں وہ یاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔’
نذرالحسن نے بتایا کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یاد کیسے کرتے ہیں، حالانکہ تھیئٹر کرنے والوں کے لیے یہ کوئی اچھنبے کی بات نہیں ہے۔
فواد خان نے بتایا کہ ‘ایک اچھی بات یہ ہے کہ متن کے بعض حصے شہوت انگیز ہوتے ہیں اور لوگ بہت کُھل کھیل کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ دیا۔’
داستان زبانی بیانیہ ہے یعنی زبانی کہانی سنانے کی روایت کو داستان گوئی کہا جاتا ہے۔ داستان اور ناول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ناول پڑھنے جبکہ داستان سنانے کے لیے لکھی جاتی ہے۔
اس خطے میں ویسے تو بہت سی داستانیں مشہور ہوئیں لیکن سب سے مشہور داستانِ امیر حمزہ تھی۔جب اسے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا تو وہ بہت پھیلتی چلی گئی۔
19 ویں صدی کے آخیر میں جب داستانِ امیر حمزہ کو چھپوانا شروع کیا گیا تو اُس کی کوئی 46 جلدیں بنیں۔ داستانِ امیر حمزہ کا ہی ایک ٹکڑا ہے طلسمِ ہوش رُبا جو نو جلدوں پر محیط ہے۔ ان 46 جلدوں کو اکٹھا کرنے اور پڑھنے اور تنقید کرنے کا کام انڈیا کے نامور نقاد شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کیا۔
16ویں صدی میں پنپنے والی داستان گوئی کی صنف کا سلسلہ ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقرعلی کا انتقال 1928 میں ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داستان گوئی کے قواعد کے بارے میں زیادہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔
ادب/فکشن کے تاریخی حوالہ جات دو ہزار قبل مسیح تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک واضح اور ہئیتی حوالے سے نسبتاً معیاری لکھت کے پیشِ نظر قدیم یونانی شاعر ہومر اورآگسٹن بادشاہوں کے دور میں رومی شاعر ورجل کی تخلیقات کو مانا جاتا ہے۔ ہومر کی “الیڈ اور اوڈیسی” دو داستانوی منظومے ہیں اور دونوں بیانیاتی سطح پر باہم منسلک ہیں۔ورجل کی “ایکلاگز اور اینی ایڈ” بھی دانستانوی منظومے یا**ایپک پوئمز** ہیں اور ان تمام کلاسک لکھتوں کا موضوع جنگ اور سفر رہا ہے۔ہندو مت میں وید اور پراکرت سب سے پرانا لٹریچر متصور ہوتا ہے اور مذہبی / قومی پس منظر میں قدیم یونانی اور مصری مخطوطے بھی ابتدائی فکشن کے نقوش وضع کرنے میں معاون ثابت ہوئے۔ہومر کی ایپک “اوڈیسی” اور “ایلیڈ” کلاسک شاہکار کا درجہ اختیار کر گئی اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ رہا کہ اس سے قبل اسطور کا اتنی بہتر تکنیک / ہئیت میں اظہارنہیں ہوا تھا۔ اوڈیسیس ایک طویل ترین سفرجس میں” ٹرائے” کا سفر بھی شامل ہے پر روانہ ہوا اور سفر کے دوران ان تمام اساطیری علائم اور سمبلز کے توسط سے کائنات کے گورکھ دھندے کو سمجھنے کی تگ و دو بھی کرتا رہا اور واپسی کے جتن بھی۔ بہرحال سفر کے دوران جوانی کا بڑھاپے میں ڈھلنا اوردس برس بعد واپس اپنے محل پہنچنے پر جوان ہوجانا سب سمبالک پیٹرن پر اسطور کو ایک بہترین نہج پر پیش کیا گیا ہے۔ ہومر کے پیٹرن نے ہی اس ایپک کو ایک معتبر ابتدائی ادبی لکھت کی ذیل میں لاکھڑا کیا۔میرے خیال سے آج ادب کے ضمن میں جو کچھ بھی لکھا جارہا ہے اس کا جوہر ہومر اور ورجل کے عظیم الشان تخلیقی فن پاروں سے کشید ہوا ہے پھر بھلے وہ نثر ہو یا نظم ۔۔۔۔۔ آپ اگر داستانوی / فکشنل نیریشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہومر سے بہترین مثال نہیں ملتی اور اگر رجزیہ / نظمیہ طمطراق اور شکوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی موصوف کی لکھتوں کی طرف نظر جاتی ہے۔
٭ آج 2018 ء میں کیا داستان گوئی دوبارہ رواج پا سکے گی ؟
٭ انگریزی میں ہیری پوٹر ( سات ناول) جیسے ناول نہ صرف لکھے گئے بلکہ انتہائی مقبول بھی ہوئے ۔ وہاں ہم سے کہیں زیادہ میکانکی سماج ہے ۔ اختصار بھی مغرب کی دین ہے ۔
افسانہ ، ناول ، فلیش فکشن سب ادھر سے تو آیا ۔
شارٹ کٹ کیا ہمارے ہی مزاج میں ہے ؟
٭ کیا یہ پرنے پیرا میٹرز نئے بیانیہ میں نہیں برتے جا سکتے؟
٭اصل مدعا یہ ہے کہ داستان کے بنیادی خدوخال کیا ہیں اور انہیں عصری نثری / افسانوی ہئیتوں میں کیوں کر پیوند کیا جاسکتا ہے؟
داستان کیا ہے؟
داستان ایسے طویل نثری قصے کو کہتے ہیں، جس کی بنیاد تخیل، رومان، جذبات اور مافوق الفطرت عناصر پر ہو۔ اور اس میں قصہ در قصہ (کئی قصے) بیاں ہوں۔
داستان کسی خیالی اور مثالی دنیا کی کہانی ہے جو محبت، مہم جوئی، سحرو طلسم، جیسے غیر معمولی عناصر پر مشتمل ہوں اور مصنف کے آزاد و زرخیز ذہن کی پیداوار ہو۔
داستان کی خصوصیات:۔
داستان میں مافوق الفطرت عناصر، واقعات، مقامات اور کرداروں کی کثرت ہوتی ہے۔ جادوں کی چیزیں، جادوں کے واقعات، خزانوں، جن ،پریوں، بھوت پریت، شہزادے، شہزادیوں کا ذکر قدم قدم پر نظر آتا ہے۔
داستان ناول یا افسانے کے برعکس ہماری خارجی دنیا سے بلند و برتر ایک مثالی اور خیالی دنیا کی کہانی ہوتی ہے، جس میں مثالی کردار بستے ہیں اور مثالی واقعات آتے ہیں جو آخر کار مثالی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔داستان کے سمجھنے کے لیے ہم قریب ترین مثال مغرب سے دے سکتے ہیں جس کا ذکر اوپر ایک سوال کے تناظر میں بھی کیا گیا ہے یعنی ” ہیری پوٹر”گو اسے وہاں ناول کے طور پر پیش کیا گیا لیکن اس کی تمام خصوصیات ہماری داستان سے ملتی جلتی ہیں۔
مثلاً:۔
٭ اس میں مافوق الفطرت عناصر، واقعات، مقامات اور کرداروں کی کثرت ہے۔
٭ اس میں قصہ در قصہ (کئی قصے) بیان ہوئے ہیں۔
٭ اس کی کہانی کسی خیالی اور مثالی دنیا کی کہانی ہے جو محبت، مہم جوئی، سحرو طلسم، جیسے غیر معمولی عناصر پر مشتمل ہے۔
٭ اس میں مثالی کردار بستے ہیں اور مثالی واقعات آتے ہیں جو آخر کار مثالی نتیجے پر پہنچتے دکھائی دیتے ہیں۔
اس ضمن میں “ہیری پوٹر” کو مثال کے طور پر پیش کرنے کا مقصد اردو داستان کو جدید منظر نامے میں دیکھنے پرکھنے کی ایک کوشش ہے۔یہاں اکثریت نے اردو داستانیں نہیں پڑھ رکھی ہوں گی لیکن “ہیری پوٹر” کو ناول کی صورت پڑھ یا فلم کی صورت ضرور دیکھ رکھا ہو گا۔داستان کے اجزاء ترکیبی سے پہلے صنفی بحث سمیٹتا چلوں ادب کی اصناف اپنی مخصوص تکنیکس اور خصوصیات کی بنا پراپنا جدا مقام رکھتی ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ پہچانی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم صرف اقتباس دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کسی ناول کا اقتباس ہے یا کسی کہانی کا یا کسی افسانے کا یا کسی داستان کا ۔میں ادب میں زیادہ سے زیادہ اور جدید سے جدید تر اصناف کے اپنانے اور برتنے کا قائل ہوں۔ تخلیق کار کے پاس تخلیق کرنے کا جتنا وسیع میدان ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ تخلیقات کے منظر عام پر آنے اور قاری تک پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں۔مغرب میں بس ادب تخلیق ہوتا ہے وہاں پاپولر ادب اور ادب ِ عالیہ یا سنجیدہ ادب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی وہاں زیادہ پڑھا جانے والا ادب پاپولر ادب بھی ہے ،سنجیدہ ادب بھی اور ادب ِ عالیہ بھی وہی ہے جیسے “ہیری پوٹر” اور اس ہی پر تنقید بھی لکھی جاتی ہے۔اردو میں ایک خاص قسم کی تفریق پائی جاتی ہے۔سنجیدہ اور پاپولر ادب میں یہاں ڈائجسٹ کی سطح کا لکھا جانے والا تمام ادب پاپولر ادب کے کھاتے میں ڈال کر رد کر دیا جاتا ہے نہ تو انہیں سنجیدہ ادبی دوڑ میں شامل کیا جاتا ہے نہ ان پر تنقید لکھی جاتی ہے نہ حوالے کے لیے ہی تذکرہ کیا جاتا ہے ۔پھر چاہے وہ فرحت عباس شاہ یا وصی کی شاعری ہو یا عمیرہ احمد اور نمرہ احمد یا رضیہ بٹ کے ناول کہانیاں ۔میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان متروک اصناف کو پھر سے برتتا ہے اور ان میں نئی چمک پیدا کر دیتا ہے تو اسے خوش آمدید کہنا چاہیے ناکہ اس کے پیچھے لٹھ لے کر دوڑ پڑنا چاہیے۔
اب چلتے ہیں داستان کے اجزائے ترکیبی کی جانب۔
٭ طوالت
داستان میں طوالت کی کوئی قید نہیں یہ ایک گھنٹے سے لیکر ایک سال یا ایک عمر تک بھی طویل ہو سکتی ہیں مثلاً مرزا رجب علی بیگ کی داستان ” فسانہء عجائب” کا شمار مختصر ترین داستانوں میں ہوتا ہے جب کہ نواب امان اللہ خاں غالب کی داستان ” امیر حمزہ” کا شمار طویل ترین داستانوں میں ہوتا ہے۔داستان کو طوالت کے لیے قصہ در قصہ آگے بڑھایا جاتا ہے جن کا مرکزی قصے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
(میری ذاتی رائے میں داستان کے احیا کے لیے اس کا مختصر ہونا ضروری ہے)
٭پلاٹ
در اصل داستان کا کوئی پلاٹ ہی نہیں ہوتا پلاٹ تو ناول کے ساتھ آیا ہے۔داستانوں میں نہ تو مربوط پلاٹ کا کوئی تصور ہے نہ واقعات میں کوئی ترتیب ۔لکھاری آزاد ہے جب چاہے مرکزہ قصہ کو چھوڑ ایک نیا قصہ شروع کر دے لیکن یہ ثانوی قصے جو مختلف وجوہاتے کی بنا پر شروع کیے جاتے ہیں شروع کرنے کے بعد مکمل کرنے لازمی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ مصنف یا داستان گو گاہے ماہے اپنے مرکزی قصے سے رجوع کرتا رہتا ہے ۔ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک داستان شروع کی جائے اس کے بعد مرکزی قصہ چھوڑ کر قصہ در قصہ داستان آگے بڑھائی جائے اور درمیان میں مرکزی قصے کو نہ شامل کیا جائے اور آخر میں مرکزی قصے پر لوٹ کر داستان ختم کر دی جائے۔
٭ کردار نگاری
داستان میں حقیقی زندگی کے فطری کردار نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ۔زیادہ تر کردار اعلٰی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔جو دیکھنے میں انسانوں جیسے ہو سکتے ہیں لیکن اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے مثالی کردار بن جاتے ہیں جیسے ایک شہزادہ دیکھنے میں انسان لیکن غائب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے مثالی کردار میں ڈھل جاتا ہے۔بہت طاقتور جنوں ، پریوں، دیووں سے مقابلہ کرنے والے کردار جو عم زندگی میں نہیں پائے جاتے۔جو انسان عام زندگی میں نہیں کر سکتے وہ سب داستانوں میں ممکن ہوتا ہے ۔یہ بھی داستان کی ایک خصوصیت ہے۔
٭مافوق الفطرت عناصر
داستان میں مرکزی کرداروں کے علاوہ فوق الفطری کردار و عناصر بھی ہوتے ہیں جیسے جن۔پری۔دیو۔جل پری۔اڑنے والے گھوڑے۔جادوئی ٹوپی۔نقش تعویز ۔اڑنے والے قالین۔ جادوئی تلوار ،تیر وغیرہ جن کا ہماری عام فطری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔یہ غیر فطری عناصر ہی داستانوں کا اہم سرمایا ہیں اور ان ہی سے ہماری داستانیں پہچانی جاتی ہیں۔اسی سے داستان کی حیرت انگیز دنیا آباد ہوتی ہے اور داستان کو دوسری اصناف سے ممیز کرتی ہے۔
٭منظر نگاری
منظر نگاری کے حوالے سے بھی داستان بہت زرخیز ہوتی ہے۔ہماری داستانیں اردو ادب کا بیش بہا اثاثہ ہیں منظر نگاری کے نقطہء نگاہ سے۔
داستان نگاروں نے مختلف ممالک کے جغرافیائی حالات۔ پہاڑ ریگزار۔بندرگاہیں۔شادی بیاہ۔عرس۔موسم۔میلے ۔ دریا۔ ایسے مناظر کا بڑی تفصیل اور سلیقے سے ذکر کیا ہے اپنی داستانوں میں کہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔
٭تہذیب و معاشرے کی عکاس
داستان تہذیب و معاشرے کی عکاس ہوتی ہے۔کہا جا سکتا ہے کہ ہماری داستانوں سے دکن و شمال ،لکھنئو و دہلی کی پوری تہذیبی اور معاشرتی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔داستان نگار اپنی تہذیب اور معاشرت کی مکمل تصویر اپنی داستان میں پیش کرتا ہے۔داستان میں رہن سہن کے آداب۔کھانے پینے کی اقسام۔ملبوسات۔سواریاں۔ ملازم۔چور اچکوے۔زیورات ۔جانور۔غرض ہر چیز کا ذکر تفصیل سے کیا جاتا ہے اپنے ثقافتی رنگ کے ساتھ۔
٭اخلاق کا درس
داستان میں اخلاق کا درس لازمی ہونا چاہیے۔داستان کا انجام طربیہ اور نصیحت وسبق آموز ہوتا ہے۔داستان میں حق کی فتح اور باطل کی شکست ہر جگہ بار بار دکھائی جاتی ہے اور داستان میں ہمدردی۔نیکی۔وفاداری۔شجاعت کا درس بھی لازمی شامل کیا جاتا ہے۔اچھے اخلاق کی تبلیغ۔اور جرات اور محبت و بھائی چارے کی تلقین کی جاتی ہے۔
٭انجام
داستان کا انجام طربیہ ہوتا ہے ہمیشہ نیکی کی فتح ہوتی ہے اور بدی کو مات ہوتی ہے داستان کا ہیرو ہر مشکل سے گزر کر آخر فتح مند ہوتا ہے ۔داستان میں ہمیں زندگی کی امیدیں امنگیں حسرتیں آرزوئیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔
٭زبان و بیان
داستانوں میں دو طرح کے اسالیب کو برتا گیا ہے ایک رنگین مسجع فارسی آمیز اور دوسرا سادہ سلیس اور با محاورہ دونوں اسالیب میں داستان نگاروں نے اپنے اپنے فن کے کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔(اس معاملے میں ،میں اسلوب کو تخلیق کار کی صوابدید پر چھوڑنے کے حق میں ہوں کوئی آج کے دور میں داستان لکھے تو کسی نئے جدید اسلوب کو بھی اپنا سکتا ہے)
ان اجزائے ترکیبی کو سمجھ کر ہم اردو داستان کی صنفی حیثیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ان کے برتاؤ سے بیانیہ کی جدید صورت گری بھی کر سکتے ہیں ہماری داستانوں نے ہی آنے والے زمانے کے فکشن کی بنیاد فراہم کی ہے جسے کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔۔۔۔
خیر اندیش